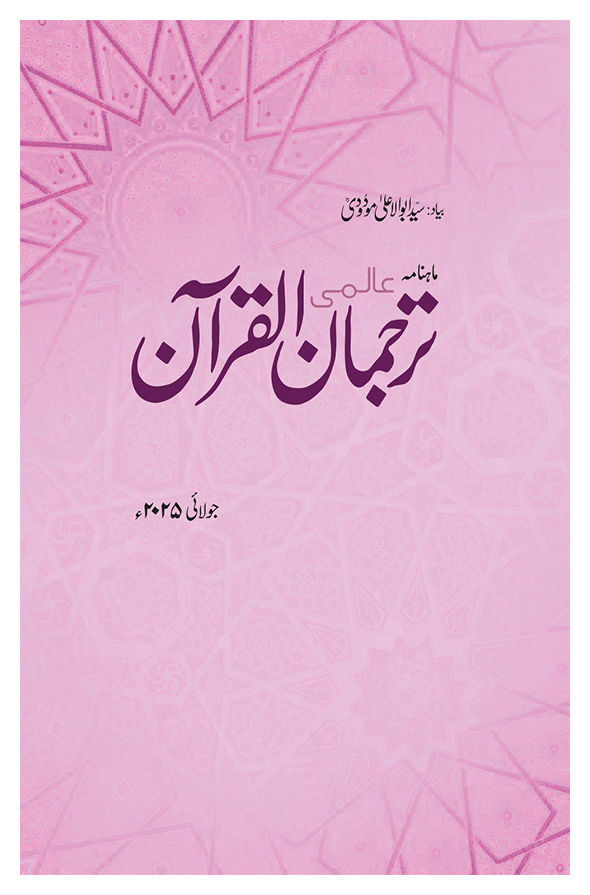
ہرسال محرم میںکروڑوںمسلمان شیعہ بھی اورسنی بھی،امام حسینؓ [شہادت:۱۰محرم ۶۱ھ] کی شہادت پراپنے رنج وغم کااظہارکرتے ہیں۔لیکن افسوس ہے کہ ان غم گساروںمیںسے بہت ہی کم لوگ اس مقصد کی طرف توجہ کرتے ہیں،جس کے لیے امامؓ نے نہ صرف اپنی جانِ عزیزقربان کی، بلکہ اپنے کنبے کے بچوںتک کوکٹوادیا۔کسی شخص کی مظلومانہ شہادت پراس کے اہل خاندان کا، اوراس خاندان سے محبت وعقیدت یاہمدردی رکھنے والوںکااظہارِغم کرناتوایک فطری بات ہے۔ ایسارنج وغم دُنیا کے ہرخاندان اوراس سے تعلق رکھنے والوںکی طرف سے ظاہرہوتاہے۔ اس کی کوئی اخلاقی قدروقیمت اس سے زیادہ نہیںہے کہ اس شخص کی ذات کے ساتھ اس کے رشتہ داروںکی اور خاندان کے ہمدردوںکی محبت کاایک فطری نتیجہ ہے۔
سوال یہ ہے کہ امام حسینؓ کی وہ کیاخصوصیت ہے [اتنی مدت] گزر جانے پر بھی ہرسال ان کا غم تازہ ہوتارہے؟ اگر یہ شہادت کسی مقصدِعظیم کے لیے نہ تھی تومحض ذاتی تعلق کی بنا پر صدیوں اس کاغم جاری رہنے کے کوئی معنی نہیںہیں۔اورخودامام کی اپنی نگاہ میںاس محض ذاتی وشخصی محبت کی کیا قدرو قیمت ہوسکتی ہے؟ انھیں اگراپنی ذات اس مقصدسے زیادہ عزیز ہوتی تووہ اسے قربان ہی کیوں کرتے؟ ان کی یہ قربانی توخوداس بات کاثبوت ہے کہ وہ اس مقصد کو جان سے بڑھ کر عزیزرکھتے تھے۔ لہٰذا، اگرہم اس مقصدکے لیے کچھ نہ کریں،بلکہ اس کے خلاف کام کرتے رہیں، تومحض ان کی ذات کے لیے گریہ وزاری کرکے، اوران کے قاتلوں پر لعن طعن کرکے قیامت کے روزنہ توہم امام ہی سے کسی دادکی اُمیدرکھ سکتے ہیںاورنہ یہ توقع رکھ سکتے ہیںکہ ان کاخدااس کی کوئی قدرکرے گا۔
اب دیکھناچاہیے کہ وہ مقصدکیاتھا؟کیاامام تخت وتاج کے لیے اپنے کسی ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتے تھے اوراس کے لیے انھوںنے سردھڑکی بازی لگائی؟
کوئی شخص بھی جوامام حسینؓ کے گھرانے کی بلنداخلاقی سیرت کوجانتاہے،یہ بدگمانی نہیںکرسکتاکہ یہ لوگ اپنی ذات کے لیے اقتدارحاصل کرنے کی خاطرمسلمانوںمیںخوں ریزی کرسکتے تھے۔اگرتھوڑی دیرکے لیے ان لوگوںکانظریہ ہی صحیح مان لیاجائے جن کی رائے میںیہ خاندان حکومت پراپنے ذاتی استحقاق کادعویٰ رکھتاتھا،تب بھی حضرت ابوبکرؓسے لے کرامیرمعاویہؓ تک، پچاس برس کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑنااورکشت وخون کرناہرگز ان کامسلک نہ تھا۔اس لیے لامحالہ یہ مانناہی پڑے گاکہ امام عالی مقام کی نگاہیںاس وقت مسلم معاشرے اوراسلامی ریاست کی روح اوراس کے مزاج اوراس کے نظام میںکسی بڑے تغیر کے آثاردیکھ رہی تھیں،جسے روکنے کی جدوجہدکرناان کے نزدیک ضروری تھا، حتیٰ کہ اس راہ میں لڑنے کی نوبت بھی آجائے تونہ صرف جائزبلکہ فرض سمجھتے تھے۔
وہ تغیرکیاتھا؟ظاہرہے کہ لوگوںنے اپنادین نہیںبدل دیاتھا۔حکمرانوںسمیت سب لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اورقرآن کواسی طرح مان رہے تھے، جس طرح پہلے مانتے تھے۔ مملکت کا قانون بھی نہیںبدلاتھا۔عدالتوںمیںقرآن اورسنت ہی کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے بنی اُمیہ کی حکومت میںبھی ہورہے تھے، جس طرح ان کے برسراقتدارآنے سے پہلے ہوا کرتے تھے، بلکہ قانون میںتغیرتوانیسویںصدی عیسوی سے پہلے دُنیاکی مسلم حکومتوںمیںسے کسی کے دور میں بھی نہیںہوا۔
بعض لوگ یزیدکے شخصی کردارکوبہت نمایاںکرکے پیش کرتے ہیں، جس سے یہ عام غلط فہمی پیداہوگئی ہے کہ وہ تغیرجسے روکنے کے لیے امام کھڑے ہوئے تھے، بس یہ تھاکہ ایک بُرا آدمی برسرِاقتدارآگیاتھا۔لیکن یزیدکی سیرت وشخصیت کاجوبرے سے بُرا تصور پیش کرناممکن ہے، اسے جوںکاتوںمان لینے کے بعدبھی یہ بات قابلِ تسلیم نہیںہے کہ اگرنظام صحیح بنیادوں پر قائم ہو تو محض ایک بُرے آدمی کابرسراقتدارآجاناکوئی ایسی بڑی بات ہوسکتی ہے، جس پرامام حسینؓ جیسا دانا وزیرک اورعلم شریعت میںگہری نظررکھنے والاشخص بےصبر ہوجائے۔ اس لیے یہ شخصی معاملہ بھی وہ اصل تغیر نہیںہے جس نے امام کوبے چین کیاتھا۔
تاریخ کے غائرمطالعے سے جوچیزواضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یزیدکی ولی عہدی اور پھراس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتداہورہی تھی، وہ اسلامی ریاست کے دستور، اوراس کے مزاج اور اس کے مقصدکی تبدیلی تھی۔اس تبدیلی کے پورے نتائج اگرچہ اس وقت سامنے نہ آئے تھے، لیکن ایک صاحب ِنظرآدمی گاڑی کارُخ تبدیل ہوتے ہی یہ جان سکتاہے کہ اب اس کاراستہ بدل رہاہے، اورجس راہ پریہ مڑرہی ہے وہ آخرکاراسے کہاںلے جائے گا۔ یہی رخ کی تبدیلی تھی، جسے امام نے دیکھااورگاڑی کوپھرسے صحیح پٹڑی پرڈالنے کے لیے اپنی جان لڑا دینے کافیصلہ کیا۔
اس چیزکوٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ہمیںدیکھناچاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ کی سربراہی میںریاست کاجونظام چالیس سال تک چلتا رہا تھا، اس کے دستور کی بنیادی خصوصیات کیاتھیں،اوریزیدکی ولی عہدی سے مسلمانوںمیںجس دوسرے نظامِ ریاست کاآغازہوا،اس کے اندرکیاخصوصیات تھیں، جو دولت بنی امیہ وبنی عباس اور بعد کی بادشاہیوں میں ظاہر ہوئیں؟اسی تقابل سے ہم یہ جان سکتے ہیںکہ یہ گاڑی پہلے کس لائن پرچل رہی تھی، اور اس نقطۂ انحراف پرپہنچ کرآگے وہ کس لائن پرچل پڑی اوراسی تقابل سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اورسیدئہ فاطمہؓ اور حضرت علیؓ کی آغوش میںتربیت پائی تھی اورجس نے صحابہؓ کی بہترین سوسائٹی میںبچپن سے بڑھاپے تک کی منزلیں طے کی تھیں،وہ کیوںاس نقطۂ انحراف کے سامنے آتے ہی گاڑی کواس نئی لائن پرجانے سے روکنے کے لیے کھڑاہوگیا،اورکیوںاس نے اس بات کی بھی پروانہ کی کہ اس زوردارگاڑی کارخ موڑنے کے لیے اس کے آگے کھڑے ہوجانے کاکیانتیجہ ہوسکتاہے؟
اسلامی ریاست کی اولین خصوصیت یہ تھی کہ اس میںصرف زبان ہی سے یہ نہیںکہاجاتا تھا بلکہ سچے دل سے یہ مانابھی جاتاتھا،اورعملی رویے سے اس عقیدے ویقین کاپورا ثبوت بھی دیا جاتا تھا کہ ملک خداکا ہے، باشندے خداکی رعیت ہیں،اورحکومت اس رعیت کے معاملے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکومت اس رعیت کی مالک نہیںہے اوررعیت اس کی غلام نہیں ہے۔ حکمرانوںکاکام سب سے پہلے اپنی گردن میںخداکی بندگی وغلامی کاقلادہ ڈالناہے، پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی رعیت پر اس کا قانون نافذ کریں۔ لیکن یزید کی ولی عہدی سے جس انسانی بادشاہی کا مسلمانوں میں آغاز ہوا، اس میں خدا کی بادشاہی کا تصور صرف زبانی اعتراف تک محدود ہوکر رہ گیا۔ عملاً اس نے وہی نظریہ اختیارکرلیا جو ہمیشہ سے ہر انسانی بادشاہی کا رہاہے، یعنی ملک بادشاہ اور شاہی خاندان کا ہے اور وہ رعیت کی جان، مال، آبرو ، ہر چیز کا مالک ہے۔ خدا کا قانون ان بادشاہتوں میں نافذ ہوا بھی تو صرف عوام پر ہوا، بادشاہ اور ان کے خاندان اور امرا اور حکام زیادہ تر اس سے مستثنیٰ ہی رہے۔
اسلامی ریاست کامقصد خدا کی زمین میں ان نیکیوں کو قائم کرنا اور فروغ دیناتھا جو خدا کو محبوب ہیں اور ان برائیوں کو دبانا اور مٹانا تھا جو خدا کو نا پسند ہیں۔ مگر انسانی بادشاہت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد حکومت کا مقصد فتح ممالک اور تسخیر خلائق اور تحصیل باج و خراج اور عیشِ دُنیا کے سوا کچھ نہ رہا۔ خدا کا کلمہ بلند کرنے کی خدمت بادشاہوں نے کم ہی کبھی انجام دی ۔ ان کے ہاتھوں اور ان کے امرااور حکام اور درباریوں کے ہاتھوں بھلائیاں کم اور برائیاں بہت زیادہ پھیلیں۔ بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کی روک تھام اور اشاعتِ دین اور علومِ اسلامی کی تحقیق و تدوین کے لیے جن اللہ کے بندوں نے کام کیا، انھیں حکومتوں سے مدد ملنی تو درکنار اکثر وہ حکمرانوں کے غضب ہی میں گرفتا ر رہے اور اپنا کام وہ ان کی مزاحمتوں کے علی الرغم ہی کرتے رہے۔ ان کوششوں کے برعکس حکومتوں اور ان کے حکام و متوسلین کی زندگیوں اور پالیسیوں کے اثرات مسلم معاشرے کو پیہم اخلاقی زوال ہی کی طرف لے جاتے رہے ۔ حد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالنے سے بھی دریغ نہ کیا، جس کی بدترین مثال بنو اُمیہ کی حکومت میں نو مسلموں پر جزیہ لگانے کی صورت میں ظاہر ہوئی۔
اسلامی ریاست کی روح تقویٰ اور خدا ترسی اور پرہیز گاری کی روح تھی، جس کا سب سے بڑا مظہر خود ریاست کا سربراہ ہوتاتھا۔ حکومت کے عمال اور قاضی اور سپہ سالار، سب اس روح سے سرشار ہوتے تھے ، اور پھر اسی روح سے وہ پورے معاشرے کو سرشار کرتے تھے، لیکن بادشاہی کی راہ پر پڑتے ہی مسلمانوں کی حکومتوں اور ان کے حکمرانوں نے قیصر و کسریٰ کے سے رنگ ڈھنگ اور ٹھاٹھ باٹھ اختیار کرلیے۔ عدل کی جگہ ظلم وجور کا غلبہ ہوتا چلا گیا۔ پرہیز گاری کی جگہ فسق و فجور اور راگ رنگ اور عیش و عشرت کا دور دورہ شروع ہوگیا۔ حرام و حلال کی تمیز سے حکمرانوں کی سیرت و کردار خالی ہوتی چلی گئی ۔ سیاست کا رشتہ اخلاق سے ٹوٹتا چلا گیا۔ خدا سے خود ڈرنے کے بجائے حاکم لوگ بندگانِ خدا کو اپنے آپ سے ڈرانے لگے اور لوگوں کے ایمان و ضمیر بیدار کرنے کے بجائے ان کو اپنی بخششوں کے لالچ سے خریدنے لگے۔
یہ تو تھا روح و مزاج اور مقصد اور نظریے کا تغیر۔ ایسا ہی تغیر اسلامی دستور کے بنیادی اصولوں میں بھی رُونما ہوا۔ اس دستور کے ساتھ اہم ترین اصول تھے ، جن میں سے ہر ایک کو بدل ڈالا گیا۔
۱- آزادانہ انتخاب:دستور اسلامی کا سنگ بنیاد یہ تھاکہ حکومت لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہو۔ کوئی شخص اپنی کوشش سے اقتدار حاصل نہ کرے بلکہ لوگ اپنے مشورے سے بہتر آدمی کو چُن کر اقتدار اس کے سپرد کردیں ۔ ’بیعت‘، اقتدار کا نتیجہ نہ ہوبلکہ اس کا سبب ہو۔ ’بیعت‘ حاصل ہونے میں آدمی کی اپنی کسی کوشش یا سازش کا دخل نہ ہو۔ لوگ ’بیعت‘ کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح آزاد ہوں ۔ جب تک کسی شخص کو ’بیعت‘ حاصل نہ ہو وہ برسرِاقتدار نہ آئے اور جب لوگوں کا اعتماد اس پر سے اٹھ جائے تو وہ اقتدار سے چمٹا نہ رہے۔ خلفائے راشدینؓ میں سے ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسرِاقتدار آیاتھا۔
امیرمعاویہ ؓ کے معاملے میں پوزیشن مشتبہ ہوگئی۔ اسی لیے صحابی ہونے کے باوجود ان کا شمار خلفائے راشدین میں نہیں کیاگیا۔ لیکن آخر کاریزید کی ولی عہدی وہ انقلابی کارروائی ثابت ہوئی جس نے اس قاعدے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اس سے خاندانوں کی موروثی بادشاہتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا، جس کے بعد سے آج تک پھر مسلمانوں کو ’انتخابی خلافت‘ کی طرف پلٹنا نصیب نہ ہوسکا۔ اب لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسراقتدار آنے لگے۔ اب بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کے بجائے اقتدار سے بیعت حاصل کی جانے لگی۔ اب بیعت کرنے یا نہ کرنے میں لوگ آزاد نہ رہے اور بیعت کا حاصل ہونا اقتدار پر قائم رہنے کے لیے شرط نہ رہا۔ لوگوں کی اوّل تو یہ مجال نہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا اس کی بیعت نہ کرتے۔ لیکن اگر وہ بیعت نہ بھی کرتے تو جس کے ہاتھ میں اقتدار آگیا تھا وہ ہٹنے والا نہ تھا۔ اسی جبری بیعت کو کالعدم قرار دینے کا قصور جب منصور عباسی کے زمانے میں اما م مالکؒ سے سرزد ہوا تو ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے اور ان کے ہاتھ شانوں سے اکھڑوا دیے گئے۔
۲- شورائی نظام:دوسرا اہم ترین قاعدہ اس دستور کا یہ تھاکہ حکومت مشورے سے کی جائے اور مشورہ ان لوگوں سے کیا جائے جن کے علم، تقویٰ اور اصابت رائے پر عام لوگوں کو اعتماد ہو۔ خلفائے راشدینؓ کے عہد میں جو لوگ شوریٰ کے رکن بنائے گئے ، اگرچہ ان کو انتخابِ عام کے ذریعے سے منتخب نہیںکرایا گیاتھا۔ جدید زمانے کے تصور کے لحاظ سے وہ نامزد کردہ لوگ ہی تھے۔ لیکن خلفا نے یہ دیکھ کر ان کو مشیر نہیں بنایاتھا کہ یہ ہماری ہاں میں ہاں ملانے، اور ہمارے مفاد کی خدمت کرنے کے لیے موزوں ترین لوگ ہیں بلکہ انھوںنے پورے خلوص اور بے غرضی کے ساتھ قوم کے بہترین عناصر کو چنا تھا، جن سے وہ حق گوئی کے سوا کسی چیز کی توقع نہ رکھتے تھے، جن سے یہ اُمید تھی کہ وہ ہر معاملے میں اپنے علم و ضمیر کے مطابق بالکل صحیح ایمان دارانہ رائے دیں گے، جن سے کوئی شخص بھی یہ اندیشہ نہ رکھتاتھاکہ وہ حکومت کو کسی غلط راہ پر جانے دیں گے ۔ اگر اس وقت ملک میں آج کل کے طریقے کے مطابق انتخابات بھی ہوتے تو عام مسلمان انھی لوگوں کو اپنے اعتماد کا مستحق قرار دیتے۔
لیکن شاہی دور کاآغاز ہوتے ہی شوریٰ کا یہ طریقہ بدل گیا۔ اب بادشاہ استبداد اور مطلق العنانی کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔اب شہزادے اور خوشامدی اہل دربار، اور صوبوں کے گورنر اور فوجوں کے سپہ سالار ان کی کونسل کے ممبر تھے ۔ اب وہ لوگ ان کے مشیر تھے جن کے معاملے میں اگر قوم کی رائے لی جاتی تو اعتماد کے ایک ووٹ کے مقابلے میں لعنت کے ہزار ووٹ آتے اور اس کے برعکس وہ حق شناس و حق گواہل علم وتقویٰ، جن پر قوم کو اعتماد تھا وہ بادشاہوں کی نگاہ میں کسی اعتماد کے مستحق نہ تھے، بلکہ الٹے معتوب یا کم ازکم مشتبہ تھے۔
۳- اظہار رائے کی آزادی:اس دستور کا تیسرا اصول یہ تھاکہ لوگوں کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اسلام نے ہر مسلمان کا حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا۔ اسلامی معاشرے اور ریاست کے صحیح راستے پر چلنے کا انحصار اس بات پر تھاکہ لوگوں کے ضمیر اور ان کی زبانیں آزاد ہوں، وہ ہر غلط کام پر بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور حق بات برملا کہہ سکیں۔
خلافت راشدہؓ میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کا یہ حق پوری طرح محفوظ تھا، بلکہ خلفائے راشدینؓ اسے ان کافرض سمجھتے تھے اور اس فرض کے ادا کرنے میں ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ ان کی مجلس شوریٰ کے ممبروں ہی کو نہیں ، قوم کے ہر شخص کو بولنے اور ٹوکنے اور خود خلیفہ سے باز پُرس کرنے کی مکمل آزادی تھی ، جس کے استعمال پر یہ لوگ ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں بلکہ داد اورتعریف سے نوازے جاتے تھے ۔ یہ آزادی ان کی طرف سے کوئی عطیہ اور بخشش نہ تھی، جس کے لیے وہ قوم پر اپنا احسان جتاتے ، بلکہ یہ اسلام کا عطا کردہ ایک دستوری حق تھا، جس کا احترام وہ اپنا فرض سمجھتے تھے ، اور اسے بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہر مسلمان پر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عائد کردہ ایک فریضہ تھا، جس کی ادائیگی کے لیے معاشرے اور ریاست کی فضا کو ہر وقت ساز گار رکھنا ان کی نگاہ میں فرائضِ خلافت کا ایک اہم جزتھا۔
لیکن بادشاہی دور کاآغاز ہوتے ہی ضمیروں پر قفل چڑھادیے گئے اور منہ بند کردیے گئے۔ اب قاعدہ یہ ہوگیاکہ زبان کھولو توتعریف میں کھولو،ورنہ چپ رہو ۔ اور تمھارا ضمیر ایسا زور آور ہے کہ حق گوئی سے تم باز نہیں رہ سکتے تو قید یا قتل کے لیے تیار ہوجائو ۔ یہ پالیسی رفتہ رفتہ مسلمانوں کو پست ہمت، بزدل اور مصلحت پرست بناتی چلی گئی ۔ خطرہ مول لے کر سچی بات کہنے والے ان کے اندر کم سے کم ہوتے چلے گئے ۔ خوشامد اور چاپلوسی کی قیمت مارکیٹ میں چڑھتی اور حق پرستی و راست بازی کی قیمت گرتی چلی گئی۔ اعلیٰ قابلیت رکھنے والے ایمان دار اور آزاد خیال لوگ حکومت سے بے تعلق ہوگئے اور عوام کا حال یہ ہوگیاکہ کسی شاہی خاندان کی حکومت برقرار رکھنے کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جذبہ باقی نہ رہا۔ ایک کو ہٹانے کے لیے جب دوسرا آیا تو انھوںنے مدافعت میں انگلی تک نہ ہلائی، اور گرنے والا جب گرا تو انھوںنے ایک لات اور رسید کرکے اسے زیادہ گہرے گڑھے میں پھینکا۔ حکومتیں جاتی اور آتی رہیں ، مگر لوگوں نے تماشائی سے بڑھ کر اس آمدورفت کے منظر سے کوئی دلچسپی نہ لی۔
۴- خدا اور خلق کے سامنے جواب دہی: چوتھا اصول، جو اس تیسرے اصول کے ساتھ لازمی تعلق رکھتاتھا، یہ تھاکہ خلیفہ اور اس کی حکومت خدا اور خلق دونوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ جہاں تک خدا کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے، اس کے شدید احساس سے خلفائے راشدینؓ پر دن کا چین اور رات کا آرام حرام ہوگیاتھااور جہاں تک خلق کے سامنے جواب دہی کاتعلق ہے، وہ ہر وقت ،ہر جگہ اپنے آپ کوعوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔
ان کی حکومت کا یہ اصول نہ تھاکہ صرف مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) میں نوٹس دے کر ہی ان سے سوال کیاجاسکتاہے، وہ ہر روز پانچ مرتبہ نماز کی جماعت میں اپنے عوام کا سامنا کرتے تھے ۔ وہ ہرہفتے جمعہ کی جماعت میں عوام کے سامنے اپنی کہتے اور ان کی سنتے تھے ۔ وہ شب و روز بازاروں میں کسی باڈی گارڈ کے بغیر،کسی ہٹو بچو کی آواز کے بغیر عوام کے درمیان چلتے پھرتے تھے۔ ان کے گورنمنٹ ہائوس (یعنی ان کے کچے مکان ) کادروازہ ہر شخص کے لیے کھلا تھا اور ہر ایک ان سے مل سکتاتھا۔ ان سب مواقع پر ہر شخص ان سے سوال کرسکتاتھا اور جواب طلب کرسکتاتھا۔ یہ محدود جواب دہی نہ تھی بلکہ کھلی اور ہمہ وقتی جواب دہی تھی ۔ یہ نمائندوں کے واسطے سے نہ تھی بلکہ پوری قوم کے سامنے براہ راست تھی۔ وہ عوام کی مرضی سے بر سراقتدار آئے تھے اور عوام کی مرضی انھیں ہٹاکر دوسرا خلیفہ ہر وقت لا سکتی تھی۔ اس لیے نہ تو انھیں عوام کا سامنا کرنے میں کوئی خطرہ محسوس ہوتاتھا اور نہ اقتدار سے محروم ہونا ان کی نگاہ میں کوئی خطرہ تھا کہ وہ اس سے بچنے کی کبھی فکر کرتے۔
لیکن بادشاہی دور کے آتے ہی جواب دہ حکومت کاتصور ختم ہوگیا۔ خدا کے سامنے جواب دہی کا خیال چاہے زبانوں پر رہ گیا ہو، مگر عمل میں اس کے آثار کم ہی نظر آتے۔ رہی خلق کے سامنے جواب دہی، تو کون مائی کا لال تھا جوان سے جواب طلب کرسکتا۔ وہ اپنی قوم کے فاتح تھے ۔ مفتوحوں کے سامنے کون فاتح جواب دہ ہوتاہے۔ وہ طاقت سے برسرِاقتدار آئے تھے اور ان کا نعرہ یہ تھاکہ جس میں طاقت ہو، وہ ہم سے اقتدار چھین لے۔ ایسے لوگ عوام کا سامنا کب کیا کرتے ہیں اور عوام ان کے قریب کہاں پھٹک سکتے تھے؟ وہ نماز بھی پڑھتے تھے تو نتھو خیرے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے محلوں کی محفوظ مسجدوںمیں، یا باہر اپنے نہایت قابلِ اعتماد محافظوں کے جھرمٹ میں۔ ان کی سواریاں نکلتی تھیں تو آگے اور پیچھے مسلح دستے ہوتے تھے اور راستے صاف کردیے جاتے تھے۔ عوام کی اور ان کی مڈ بھیڑ کسی جگہ ہوتی ہی نہ تھی۔
۵- بیت المال، ایک امانت:پانچوا ں اصول اسلامی دستور کا یہ تھاکہ بیت المال خدا کا مال اور مسلمانوں کی امانت ہے، جس میں کوئی چیز حق کی راہ کے سوا کسی دوسری راہ سے آنی نہ چاہیے ، اور جس میں سے کوئی چیز حق کے سوا کسی دوسری راہ میں جانی نہ چاہیے۔ خلیفہ کا حق اس مال میں اتنا ہی ہے جتنا قرآن کی رُو سے مالِ یتیم میں اس کے ولی کا ہوتاہے کہ وَمَنْ کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفُ ج وَمَنْ کَانَ فَقِیْرًا فَلْیَاکُلُ بِالْمَعْرُوْفِ ط (جواپنے ذاتی ذرائع آمدنی اپنی ضرورت بھر رکھتا ہو وہ اس مال سے تنخواہ لیتے ہوئے شرم کرے، اور جو واقعی حاجت مند ہو وہ اتنی تنخواہ لے جسے ہر معقول آدمی مبنی بر انصاف مانے ۔ النساء۴:۶)۔ خلیفہ اس کی ایک ایک پائی کے آمد وخرچ پر حساب دینے کا ذمہ دار ہے اور مسلمانوں کو اس سے حساب مانگنے کا پورا حق ہے۔
خلفائے راشدینؓ نے اس اصول کو بھی کمال درجہ دیانت اور حق شناسی کے ساتھ برت کر دکھایا۔ ان کے خزانے میں جو کچھ بھی آتاتھا ٹھیک ٹھیک اسلامی قانون کے مطابق آتاتھا، اور اس میں سے جو کچھ خرچ ہوتاتھا، بالکل جائز راستوں میں ہوتاتھا۔ ان میں سے جو غنی تھا اس نے ایک حبہ اپنی ذات کے لیے تنخواہ کے طور پر وصول کیے بغیر مفت خدمت انجام دی، بلکہ اپنی گرہ سے قوم کے لیے خرچ کرنے میں بھی دریغ نہ کیا۔ اور جو تنخواہ کے بغیر ہمہ وقتی خدمت گار نہ بن سکتے تھے، انھوںنے اپنی ضروریاتِ زندگی کے لیے اتنی کم تنخواہ لی کہ ہر معقول آدمی اسے انصاف سے کم ہی مانے گا ، زیادہ کہنے کی جرأت ان کا دشمن بھی نہیں کرسکتا۔ پھر اس خزانے کی آمد و خرچ کا حساب ہروقت ہر شخص مانگ سکتاتھا اوروہ ہر وقت ہرشخص کے سامنے حساب دینے کے لیے تیار تھے۔ ان سے ایک عام آدمی بھرے مجمع میں پوچھ سکتاتھا کہ خزانے میں یمن سے جو چادریں آئی ہیں ان کا طول و عرض تو اتنا نہ تھا کہ جناب کا لمبا کُرتہ بن سکے، یہ زائد کپڑا آپ کہاں سے لائے ہیں؟
مگر جب خلافت بادشاہی میں تبدیل ہوئی تو خزانہ خدا اور مسلمانوں کانہیں بلکہ بادشاہ کا مال تھا، ہرجائز و ناجائز راستے سے اس میں دولت آتی تھی اور ہر جائز و ناجائز راستے میں بے غل و غش صرف ہوتی تھی ۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے حساب کا سوال اٹھاسکے ۔ سارا ملک ایک خوانِ یغما تھا جس پر ایک ہر کارے سے لے کر سربراہ مملکت تک ، حکومت کے سارے کل پرزے حسب توفیق ہاتھ مار رہے تھے ، اور ذہنوں سے یہ تصور ہی نکل گیاتھاکہ اقتدار کوئی پروانۂ اباحت نہیں ہے، جس کی بدولت یہ لُوٹ مار ان کے لیے حلال ہو، اور پبلک کا مال کوئی شیرِ مادر نہیں ہے، جسے وہ ہضم کرتے رہیں اور کسی کے سامنے انھیں اس کا حساب دینا نہ ہو۔
۶- قانون کی حکومت:چھٹا اصول اس دستور کا یہ تھاکہ ملک میں قانون (یعنی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون) کی حکومت ہونی چاہیے۔ کسی کوقانون سے بالاتر نہ ہوناچاہیے۔ کسی کو قانون کے حدودسے باہر جا کر کام کرنے کا حق نہ ہونا چاہیے۔ ایک عامی سے لے کر سربراہ مملکت تک، سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے اور سب پر اسے بے لاگ طریقے سے نافذ ہونا چاہیے۔ انصاف کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ ہونا چاہیے اور عدالتوں کو انصاف کرنے کے لیے ہر دبائو سے بالکل آزاد ہونا چاہیے۔
خلفائے راشدینؓ نے اس اصول کی پیروی کابھی بہترین نمونہ پیش کیاتھا۔ بادشاہوں سے بڑھ کر اقتدار رکھنے کے باوجود وہ قانونِ الٰہی کی بندشوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ نہ ان کی دوستی اور رشتہ داری قانون کی حد سے نکل کر کسی کو کچھ نفع پہنچا سکتی تھی اور نہ ان کی ناراضی کسی کو قانون کے خلاف کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ کوئی ان کے اپنے حق پر بھی دست درازی کرتا تو وہ ایک عام آدمی کی طرح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اور کسی کو ان کے خلاف شکایت ہوتی تو وہ استغاثہ کرکے انھیں عدالت میں کھینچ لا سکتا تھا۔ اسی طرح اُنھوںنے اپنی حکومت کے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی قانون کی گرفت میں کس رکھاتھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ عدالت کے کام میں کسی قاضی پر اثر انداز ہونے کا خیال بھی کرتا۔ کسی کا یہ مرتبہ نہ تھا کہ قانون کی حد سے قدم باہر نکال کر مواخذے سے بچ جاتا۔
لیکن خلافت سے بادشاہی کی طرف انتقال واقع ہوتے ہی اس قاعدے کے بھی چیتھڑے اڑ گئے۔ اب بادشاہ اور شہزادے اور امرا اورحکام اور سپہ سالار ہی نہیں ، شاہی محلات کے منہ چڑھے لونڈی غلام تک قانون سے بالا تر ہوگئے۔ لوگوں کی گردنیں اور پیٹھیں اور مال اور آبروئیں، سب ان کے لیے مباح ہوگئیں۔ انصاف کے دومعیار بن گئے: ایک کمزور کے لیے اور دوسرا طاقت ور کے لیے۔ مقدمات میں عدالتوں پر دبائو ڈالے جانے لگے اور بے لاگ انصاف کرنے والے قاضیوں کی شامت آنے لگی، حتیٰ کہ خدا ترس فقہا نے عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے کوڑے کھانا اور قید ہوجانا زیادہ قابلِ ترجیح سمجھا،تاکہ وہ ظلم و جور کے آلہ ٔ کار بن کر خدا کے عذاب کے مستحق نہ بنیں۔
۷-حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات:مسلمانوں میں حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات ، اسلامی دستور کا ساتواں اصول تھا، جسے ابتدائی اسلامی ریاست میں پوری قوت کے ساتھ قائم کیاگیاتھا۔ مسلمانوں کے درمیان نسل، وطن، زبان وغیرہ کاکوئی امتیاز نہ تھا ۔قبیلے اور خاندان اور حسب و نسب کے لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ تھی۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سب لوگوں کے حقوق یکساں تھے اور سب کی حیثیت برابر تھی۔ ایک کو دوسرے پر ترجیح اگر تھی تو سیرت واخلاق اور اہلیت و صلاحیت، اور خدمات کے لحاظ سے تھی۔
لیکن خلافت کی جگہ جب بادشاہی نظام آیا تو عصبیت کے شیاطین ہر گوشے سے سراُٹھانے لگے۔ شاہی خاندان اور ان کے حامی خانوادوں کا مرتبہ سب سے بلند و برتر ہوگیا۔ ان کے قبیلوں کو دوسرے قبیلوں پر ترجیحی حقوق حاصل ہوگئے۔ عربی اورعجمی کے تعصبات جاگ اُٹھے اور خود عربوں میں قبیلے اور قبیلے کے درمیان کش مکش پیدا ہوگئی۔ ملت اسلامیہ کو اس چیز نے جو نقصان پہنچایا اس پر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔
یہ تھے وہ تغیرات جو اسلامی خلافت کو خاندانی بادشاہت میں تبدیل کرنے سے رونما ہوئے۔ کوئی شخص اس تاریخی حقیقت کا انکار نہیںکرسکتا کہ یزید کی ولی عہدی ان تغیرات کا نقطۂ آغاز تھی، اور اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ اس نقطے سے چل کر تھوڑی مدت کے اندر ہی بادشاہی نظام میں وہ سب خرابیاں نمایاں ہوگئیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ جس وقت یہ انقلابی قدم اٹھایا گیاتھا، اس وقت یہ خرابیاں اگرچہ بہ تمام و کمال سامنے نہ آئی تھیں، مگر ہرصاحبِ بصیرت آدمی جان سکتاتھاکہ اس اقدام کے لازمی نتائج یہی کچھ ہیں اور اس سے ان اصلاحات پر پانی پھر جانے والا ہے جو اسلام نے سیاست و ریاست کے نظام میں کی ہیں۔
اسی لیے امام حسینؓ اس پر صبر نہ کرسکے اور انھوںنے فیصلہ کیا کہ جو بدترسے بدتر نتائج بھی انھیں ایک مضبوط جمی جمائی حکومت کے خلاف اٹھنے میں بھگتنے پڑیں، ان کاخطرہ مول لے کر بھی انھیں اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کوشش کا جوانجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ مگر امام نے اس عظیم خطرے میں کود کر اور مردانہ وار اس کے نتائج کو انگیز کرکے جوبات ثابت کی وہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات اُمت مسلمہ کا وہ بیش قیمت سرمایہ ہیں، جسے بچانے کے لیے ایک مومن اپنا سربھی دے دے اور اپنے بال بچوں کو بھی کٹوا بیٹھے تو اس مقصد کے مقابلے میں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، اور ان خصوصیات کے مقابلے میں وہ دوسرے تغیرات جنھیں اوپر نمبروار گنایا گیاہے، دین اور ملت کے لیے وہ آفتِ عظمیٰ ہیں جسے روکنے کے لیے ایک مومن کو اگر اپنا سب کچھ قربان کردینا پڑے تو اس میں دریغ نہ کرناچاہیے۔
کسی کا جی چاہے تو اسے حقارت کے ساتھ ایک سیاسی کام کہہ لے، مگر حسینؓ ابن علیؓ کی نگاہ میں تو یہ سراسر ایک دینی کام تھا، اسی لیے انھوںنے اس کام میں جان دینے کو شہادت سمجھ کر جان دی۔
صنعتی انقلاب کے نتیجے میں روز افزوں متنوع صنعت گاہوں کے قیام اور نت نئے تیزرفتار ذرائع آمدورفت کی مسلسل ایجادات نے گذشتہ کئی عشروں سے ماحول کے تحفظ کو عالمی توجہ کا موضوع بنا دیا ہے، کیوں کہ ماحول کی آلودگی انسانی صحت اور زندگی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ وہ زمین جس پر انسان رہتا اور بستا ہے اس کے بعض حصوں پر غلاظتوں اور گندگی کا اتنا انبار ہے کہ انسانی زندگی اس کے تعفن سے اذیت میں مبتلا ہے۔ صنعتی ترقی کے لیے جنگلوں اور پیڑوں کے غیرمتناسب استعمال بلکہ استحصال نے موسمی تغیرات کا رخ بدل دیا ہے۔ وہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں صنعت گاہوں، کارخانوں اور کیمیاوی تجربہ گاہوں کے چھوڑے ہوئے فضلات اور بڑی چھوٹی موٹرگاڑیوں کی لمبی قطاروں کی کثافتوں سے اس حد تک زہرآلود ہوچکی ہے کہ انسان تنفس ، پھیپھڑے، جگر ، قلب اور جلد کی اَن گنت بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ جانور اور پرندے بھی اس سے متاثر ہورہے ہیں اور نت نئی بیماریاں جغرافیائی حدود کو پار کررہی ہیں۔
یہاں تک کہ اوزون پرت (Ozone layer) جو سورج کی شعاعوں کے مضر اثرات سے ہماری زمین کی فضا کی حفاظت کرتی ہے، اس میں سوراخ ہورہا ہے اور انسانی زندگی کے لیے خطرات روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ وہ پانی جسے انسان خود پیتا ہے اور اپنے مویشیوں کو پلاتا اور کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، اس میں کیمیاوی مادوں اور زہریلے فضلات کی آمیزش اس قدر ہورہی ہے کہ پانی کے جانداروں کے ساتھ ساتھ انسانی جسم و جان میں بھی زہریلے اثرات منتقل ہورہے ہیں اور وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہورہا ہے۔ کسی صنعتی شہر میں دن گزار کر جب آپ گھرلوٹیں تو اپنے لباس اور جسم پر اور اپنے منہ اور ناک میں کثافتوں کی سیاہی واضح طور پر محسوس کرسکتے ہیں۔
قومی اور بین الاقوامی جنگوں میں آتشیں ہتھیاروں کے بے دریغ استعمال کے علاوہ بڑے پیمانے پر کیمیاوی گیسوں، بارودی مواد اور لیزر کی شعاعوں کا استعمال بھی کیاجانے لگا ہے۔ یہ تباہ کن ہتھیار صرف اپنے نشانہ کو ہی برباد نہیں کرتے بلکہ ایک خاص فاصلے تک پائے جانے والے ہرجاندار اور مجموعی ماحول پر بھی انتہائی مضر اثرات مرتب کرتے ہیں، جو زمین کا نمو ختم کرکے اس میں زہر بھر دیتے ہیں اور درجۂ حرارت بڑھا کر ماحول کا توازن بگاڑ دیتے ہیں۔
اس صورتِ حال میں حکومتوں، عالمی تنظیموں، رفاہی انجمنوں، علمی اور تحقیقاتی اداروں کی تشویش بجا اور برملا ہے۔ ہر طرف سے یہ مطالبہ ہورہا ہے کہ ماحول کا تحفظ کیا جائے، صاف ستھری فضا کو برقرار رکھنے کے لیے آلودگی پر قابو پایا جائے۔ معروضی غفلت کی وجہ سے انسان کو کسی چیز کی حفاظت کا احساس عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب اس کے وجود اور صحت کو خطرہ لاحق ہو۔ آنکھ میں درد ہوتا ہے تو انسان آنکھ کی فکر کرتا ہے۔ ہاتھ پائوں میں تکلیف ہوتی ہے تو انسان مالش اور معالج کی فکر کرتا ہے، ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے۔ غرض یہ کہ اصلاح کی فکر اس وقت ہوتی ہے جب فساد نظر آنے لگتا ہے۔ ماحولیات کی اصلاح اور پاکیزگی کی فکر بھی انسان کو اس وقت ہورہی ہے جب ماحول میں فساد اور کثافت پھیل گئی ہے اور لوگ اس کی زہرناکی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔
ذرا تصور کیجیے کہ آج سے چودہ سو برس پہلے جب نہ تو موٹر گاڑیوں کا وجود تھا اور نہ دیوہیکل کارخانے وجود میں آئے تھے۔ نہ جنگلات فنا ہورہے تھے اور نہ دریائوں میں زہر گھل رہا تھا۔ اور ماحول میں آلودگی تو آج کی طرح رچی بسی ہی نہ تھی۔ مگر چونکہ محمدصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے جن کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول مبعوث ہونے والا نہیں تھا۔ اس لیے قیامت تک آنے والے تمام حالات و تحدیات (چیلنجز) میں اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ کی ہدایت و رہنمائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فراہمی ناگزیر تھی کیوں کہ ان ہدایات کے بغیر نہ دین مکمل ہوتا نہ ہرانسان کے لیے دین اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کے فریضے کی ادائیگی ممکن ہوتی جسے اللہ ربّ العزت نے ہر انسان کی دُنیا و آخرت میں کامیابی کا معیار مقرر فرمایا تھا (البقرہ ۲:۲۰۸)۔ اس لیے اللہ کے آخری رسول محمدصلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ماحول کو کثافت سے پاک رکھنے اور فضا کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کی جامع تعلیم و تلقین فرمائی۔ اصولی ہدایات، مؤثر تعلیمات اور عملی اقدامات، تینوں طرح سے ماحول کی پاکیزگی کو یقینی بنایا۔ یہ کائنات انسانوں کے لیے خالقِ حقیقی کی صناعی کا خوب صورت تحفہ ہے اور اس کی تمام جاندار اور بے جان چیزیں انسانوں کے لیے ربّ العزت کی حسین نعمت ہیں۔ اس کائنات کی خوب صورتی اور تازگی کی حفاظت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تعلیم دی بلکہ اسے فروغ دینے میں اپنی تمام تر قوت و صلاحیت لگانے کی ضرورت کا احساس دلایا، اور فطرت کے عطیات کو فطری قوانین کے مطابق برتنے کی تلقین فرمائی، تاکہ انسان خود بھی ماحول کی پاکیزگی سے لطف اندوز ہوسکے اور دوسرے جانداروں کو بھی راحت پہنچا سکے اور ربِّ کریم کا شکر ادا کرے:
مَا يُرِيْدُ اللہُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَہِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَہٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۶ (المائدہ۵:۶) اللہ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے تاکہ تم شکرگزار بنو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان و زمین، سمندر، پہاڑ، حیوانات، نباتات، پرندے، جنگلات، باغات، وادیوں اور آبادیوں، سب کچھ کو خالقِ کائنات کے متوازن نظام کا شاہکار قرار دیتے ہوئے ان کی تخلیق پر غور کرنے، ان میں کارفرما ربّ العزت کی حکمتوں کو سمجھنے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تعلیم فرمائی۔ آپؐ نے انسانوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچایا:
اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّہَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللہُ مِنَ السَّمَاۗءِ مِنْ مَّاۗءٍ فَاَحْيَا بِہِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِہَا وَبَثَّ فِيْہَا مِنْ كُلِّ دَاۗبَّۃٍ ۰۠ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ۱۶۴ (البقرہ۲:۱۶۴) بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کی نفع رسانی کا سامان لیے سمندر میں چلتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو زندہ کردیتا ہے اور ہر طرح کی جاندار مخلوق کو زمین میں پھیلانے میں، اور ہوائوں کی گردش میں اور آسمانوں و زمین کے درمیان مسخر بادلوں میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
قرآن حکیم کی اس آیت میں دس چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا تعلق براہِ راست ماحولیات سے ہے:
۱- آسمان
۲- زمین
۳- دن اور رات یعنی وقت
۴-جہازرانی ۵-سمندر کے سینے پر چلنے والے سفینوں میں انسانوں کی نفع رسانی
۶-بارش ۷-زمین کی روئیدگی، کاشت کاری اور شجرکاری
۸-حیوانات کی زندگی
۹-ہوائوں کی گردش
۱۰- بادلوں کا فضا میں معلق ہونا۔
کثیرجہتی ماحولیاتی نظام کے اُن عجائبات اور ان کا انسان کے معاشرتی ماحول اور اس کی راحت رسانی کے تعلق کو، قرآن پاک میں بار بار مشاہدہ، مطالعہ اور سبق آموزی کے لیے انسانوں کے سامنے پیش کیا گیاہے۔ اس آیت میں بھی ان حکمتوں کو سمجھنے اور ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت کا احساس دلایا گیا ہے کیوں کہ اس سے انسانی زیست کے ماحول کی تشکیل ہوتی ہے اور توازن برقرار رہتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربّ العزت کا یہ سبق بھی انسانوں کو ذہن نشین کرایا ہے کہ کائنات کی ان ساری چیزوں کو خاص اہتمام ، انداز، توازن اور اعتدال کے ساتھ بنایا اور سنوارا جانا بامقصد ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مواقع پر کائنات کے نظم وتوازن اور اللہ کے مقرر کردہ معیار و مقدار پر غوروفکر کو حق تک رسائی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے:
اِنَّ اللہَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى۰ۭ يُخْرِجُ الْـحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْـحَيِّ۰ۭ ذٰلِكُمُ اللہُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ۹۵ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۰ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْـبَانًا۰ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ۹۶ (الانعام ۶:۹۵-۹۶) بے شک دانے اور گٹھلی کو (زمین میں) پھاڑنے والا اللہ ہے۔ وہی زندہ کو مُردہ سے نکالتا ہے۔ اور وہی مُردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ اللہ کے کرشمے ہیں، تم کدھر بہکے جارہے ہو؟ رات کے پردہ سے وہی دن نکالتا ہے اور اسی نے رات کو وجۂ سکون بنایا ہے اور شمس و قمر کی گردش مقرر کی ہے۔ یہ اسی غالب اور علم رکھنے والے اللہ کے ٹھیرائے ہوئے قوانین ہیں۔
دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى۱ۙ الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى۲۠ۙ وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَہَدٰى۳۠ۙ وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى۴۠ۙ (الاعلٰی۸۷: ۱ - ۴) اپنے ربّ برتر کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے اندازہ مقرر کیا اور راہ دکھائی اور جس نے نباتات اُگائیں۔
ربّ العزت نے جس طرح اپنی تخلیق میں تناسب، توازن اور اعتدال کا اہتمام رکھا ہے اس کا تاکیدی حکم ہے کہ بندے بھی اسی طرح اپنے عمل میں اعتدال و توازن رکھیں اور اللہ کے نظامِ تخلیق کا توازن نہ بگاڑیں۔ ربّ العزت کے مقرر کردہ اس توازن کی حکمت کو سمجھنا، اسے اپنی عملی سرگرمیوں کے لیے رہنما بنانا، اسے اپنی نفع رسانی سے جوڑنا، اس سے استفادہ کرنا، اس کا توازن برقرار رکھنا، اس میں خلل پیدا نہ کرنا، انسان کی ضرورت بھی ہے اور ذمہ داری بھی:
اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْـبَانٍ۵۠ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ۶ وَالسَّمَاۗءَ رَفَعَہَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ۷ۙ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ۸ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ۹ وَالْاَرْضَ وَضَعَہَا لِلْاَنَامِ۱۰ۙ فِيْہَا فَاكِہَۃٌ۰۠ۙ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ۱۱ۖ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ۱۲ۚ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ۱۳ (الرحمٰن ۵۵:۵-۱۳)سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اسی نے بلند کیا اور توازن قائم فرمایا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا۔ اس میں ہرطرح کے پھل ہیں۔ کھجور کے درخت ہیں، جن کے پھل غلافوں میں ہیں، ہر طرح کے غلّے ہیں جن میں بھوسا بھی ہے اور دانہ بھی، تو اے جنِّ و انس! تم اپنے ربّ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائو گے؟
آیت میں شمس و قمر کی گردش کا حساب ، پیڑ پودوں کی شادابی، آسمان کی بلندی، زمین کی تخلیق، غلّے اور پھل پھول کی پیدائش جیسی نعمتوں کو انسان کے سپرد کرنے کے ساتھ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ قدرت کے ایک متوازن نظام اورمعتدل انتظام کا حصہ ہیں۔ اس نظام میں خلل ڈالنے اور اس حُسنِ انتظام میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ کے عطیات سے اگر ربّ العزت کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق استفادہ کیا جائے تو یہ اصلاح ہے اور اگر ان اصولوں سے انحراف کیا جائے تو یہ فساد کا باعث ہے۔ ربّ العزت صرف عطیات ہی عطا نہیں کرتے بلکہ طریقۂ استعمال کی ہدایات بھی دیتے ہیں۔ انسان ربّ العزت کے ان عطیات سے کماحقہٗ استفادہ صرف ربّ العزت کی ہدایات کے مطابق ہی کرسکتا ہے۔
قرآن مجید میں صاف اور صریح لفظوں میں تاکید کی گئی ہے کہ ماحول میں فساد نہ کرو: وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِہَا (الاعراف ۷: ۵۶) ’’اور زمین میںاس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو‘‘۔فساد اور اصلاح قرآنِ کریم کی دو اہم اصطلاحیں ہیں جو بڑی معنی خیز ہیں۔ اصلاح کے معنی اللہ کی تخلیق کردہ فطری ترتیب، نظام اور توازن کے ہیں، یعنی ہرچیز کو اپنی فطری جگہ پر قائم رکھنا، اور فساد کے معنی اس فطری ترتیب اور توازن و نظم میں انتشار، خلل اور بگاڑ پیدا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ربّ العزت نے کائنات میں ہر چیز اندازے، قرینے، اہتمام اور اعتدال کے ساتھ رکھی ہے۔ اس میں اپنی بے راہ روی اور بداعمالی سے خلل نہ ڈالو، بگاڑ نہ پیدا کرو۔ اس کا استعمال اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کرو۔ ماحول کے اس نظم و توازن کا فائدہ خود انسانوں کو ہوگا اور اگر وہ اس میں بگاڑ پیدا کرے گا تو اس کے نقصانات اور مضر اثرات بھی اسی کو بھگتنے پڑیں گے۔ اس طرح انسان اپنی تباہی کا آپ ہی ذمہ دار ہوگا، ارشاد خداوندی ہے:
ظَہَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَہُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّہُمْ يَرْجِعُوْنَ۴۱(الروم ۳۰:۴۱) خشکی اور تری میں فساد برپا ہوگیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ اُن کو اُن کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ باز آجائیں۔
فساد کا ایک عمومی مطلب تو یہ ہے کہ انسانوں نے اپنے باغیانہ خیالات اور سرکشی اور باہم تنازع و تصادم کرکے زمین میں فساد برپا کرلیا ہے۔ مگر اس آیت کا اہم مصداق ماحول بھی ہے جس کے لیے خاص طور پر زمین کے ساتھ ساتھ بحریعنی دریا و سمندر کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی ماحول میں آلودگی، فکروخیال اور اعمال کی گندگی، بداخلاقی اور کج روی کی وجہ سے بھی ہے اور ربّ العزت کے عطیات کے غلط استعمال اور استحصال اور ان میں انسانی کثافتوں کی آمیزش کی وجہ سے بھی ہے۔ ماحول کی آلودگی اسی وقت دُور ہوسکتی ہے کہ انسان اپنے فکروعمل کا قبلہ درست کرے اور کائنات کے تعلق بارے اپنے رویے میں مثبت تبدیلی لائے۔
قرآن اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اصولی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماحولیات کے متعلق متعین ہدایات بھی انسانوں کو دربارِ نبوت سے ملتی ہیں۔ ماقبل صنعتی عہد میں ماحول کی آلودگی ابتدائی اور سادہ شکل میں پائی جاتی تھی، مگر رسولؐ اللہ نے ماحول کی آلودگی بارے انسانی شعور کو بیدار کیا اور عملی اقدامات سے متعلق جامع اور واضح ہدایات فرمائیں۔یہ ہدایات آج بھی ماحولیات کے تحفظ اور پاکیزگی کے لیے رہنما خطوط اور سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔
ماحول کے تحفظ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی حکم یہ ہے کہ گندگی پھیلانے سے پرہیز کیا جائے، خاص طور پر پبلک مقامات کو گندگی سے بچایا جائے۔ رسولؐ اللہ نے سایہ دار درخت کے نیچے، راستے میں اور مسجد میں گندگی پھیلانے سے منع فرمایا۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوچیزوں سے پرہیز کرو ۔صحابہؓ نے پوچھا: وہ موجب ِ لعنت چیزیں کیا ہیں؟ آپؐ نے فرمایا کہ لوگوں کے راستے میں اور سایہ میں غلاظت کی جائے۔( صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب النہی عن الاستنجاء بالیمین)
پبلک مقام کی جامع شکل عہد نبویؐ میں مسجد تھی۔ چنانچہ آپؐ نے مسجد میں تھوکنے سے بھی منع فرمایا۔(سنن النسائی ، کتاب المساجد، باب البصاق فی المسجد)
قربانی کے دنوں میں بڑی تعداد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ سماجی شعور کی کمی کی وجہ سے قربانی کے فضلات سڑکوں پر اور نالیوں میں بکھرے نظر آتے ہیں، گندگی پھیلتی ہے، بیماری بڑھتی ہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ قربانی کے فضلات کو دفن کر دیا جائے۔ اگر اس ہدایت پر عمل درآمد ہو تو ماحول کی آلودگی سے بچا جاسکتا ہے۔ شریعت محمدیؐ نے ایسے ایندھن کے استعمال سے روکا ہے جس کا دھواں پڑوسی کے گھر میں جاتا ہو۔ فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے یہ حکم ایک اصول اور کلیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس کی روشنی میں آج کل کی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے دھوئیں کو ضابطہ کا پابند بنایا جاسکتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماحولیاتی تعلیم و تربیت کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ روح، جسم، لباس اور مکان کے ساتھ ماحول کی صفائی کا پورا اہتمام کیا جائے۔ مسلمانوں کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ صفائی کا خاص اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اہل قباء کی یوں تعریف کی گئی:
فِيْہِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَہَّرُوْا۰ۭ وَاللہُ يُحِبُّ الْمُطَّہِّرِيْنَ۱۰۸ (التوبہ ۹:۱۰۸) اس (قباء)میں وہ لوگ ہیں جو پاکی اور صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اللہ پاک اور صاف لوگوں سے محبت کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا اور فرمایا: النَّظَافَۃُ تَدْعُوْ اِلَی الْاِیْمَانِ وَالْاِیْمَانُ مَعَ صَاحِبِہِ فِی الْجَنَّۃِ (معجم الاوسط للطبرانی، باب العین، باب المیم من اسمہ محمد، حدیث: ۷۴۵۰) ’’صفائی ایمان کی طرف لے جاتی ہے اور ایمان اپنے ساتھی کو جنّت میں لے جاتا ہے‘‘۔
ہرانسان جنّت میں جانےکا آرزومند ہے۔ ہرشخص جنّت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے ایمان و عمل سے تیاری کرتا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی تعلیم پر غور کیجیے کہ اگر جنّت میں گھر بنانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے ماحول کو پاک صاف کرکے جنّت نشان بنائو تاکہ تم صحیح معنوں میں جنّت کے حق دار بن سکو۔
قرآن و سنت کی اس صحت آفریں تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہرمسلمان اپنے ماحول کو پاک و صاف رکھنے کی فکر کرے۔ اپنے محلّہ اور بستی میں صفائی کی مہم چلائے اور گندگی جمع نہ ہونے دے ۔ وہ یہ بھی دیکھے کہ کہیں اس کی بے توجہی جراثیم کے پھیلنے اور فضائی آلودگی کا سبب تو نہیں بن گئی ہے۔اس کے گھر کے باہر ایسا کوڑا تو نہیں جمع رہتا ہے جو دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنے۔ اگر ایسا ہے تو پہلی توجہ صفائی ستھرائی پر دینی چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماحولیاتی تعلیم کا تیسرا اہم پہلو بقدرِ ضرورت استعمال کا نظریہ ہے جسے Conservationکہا جاتا ہے۔ دُنیا کی ہرچیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے استعمال کے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے:
وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا (الجاثیہ۴۵: ۱۳) اللہ نے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں تمھارے (استعمال کے)لیے مسخر کردی ہیں۔
ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:
ہُوَالَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِہَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِہٖ۰ۭ وَاِلَيْہِ النُّشُوْرُ۱۵(الملک۶۷: ۱۵) وہ اللہ ہی ہے جس نے تمھارے لیے زمین کو تابع بنایا، اس کی راہوں میں چلو، اس کا دیا ہوا رزق کھائو اور اسی کی طرف تم کو اُٹھایا جانا ہے۔
اللہ ربّ العزت نے اپنی نعمتیں انسان کو استعمال کے لیے دی ہیں مگر ان کا استعمال، سلیقہ اور طریقہ سے ہونا چاہیے، بقدرِ ضرورت ہونا چاہیے۔ نہ تو بلاضرورت ہونا چاہیے اور نہ ضرورت سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ماحول میں توازن برقرار رکھنے کے لیے استعمال نہ کہ اسراف کے لیے۔ اسراف سے بچنے کی حکیمانہ تعلیم ایک خوب صورت تناظر میں اس طرح دی گئی ہے:
وَہُوَالَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُہٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِہًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِہٍ۰ۭ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِہٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّہٗ يَـوْمَ حَصَادِہٖ۰ۡۖ وَلَا تُسْرِفُوْا۰ۭ اِنَّہٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ۱۴۱(الانعام ۶: ۱۴۱) وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اُگائیں جن سے قسم قسم کے ماکولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھائو ان کی پیداوار، جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب اُن کی فصل کاٹو، اوراستعمال میں حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
قرآن کریم میں مزید واضح لفظوں میں تاکید کی گئی ہے کہ:
وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا۰ۚ اِنَّہٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ۳۱ (الاعراف۷:۳۱) اور کھائو، پیو مگر اسراف (استعمال میں حد سے گزرنا) نہ کرو کیوں کہ اللہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔
’استعمال نہ کہ اسراف‘ کے اس بنیادی اصول کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ماحولیات میں عدم توازن کا مسئلہ پیدا ہی نہ ہو اور اس اصول کو موجودہ صورتِ حال میں مسلسل اپنانے سے ماحولیاتی آلودگی اور عدم توازن کا مسئلہ ایک معقول مدت میں حل بھی ہوسکتا ہے۔ پانی، جنگلات، حیوانات، پرندے، معدنیات، توانائی ، قدرتی وسائل اور خورونوش اور استعمال کی تمام ضروری اشیا میں بقدرِ ضرورت استعمال (Conservation) کا اصول تحفظ اور توازن کا ماحول پیدا کرے گا اور انسان جن پریشانیوں میں مبتلا ہے اس سے نکلنے کا راستہ پاسکے گا۔ اللہ کے اس حکم کے مخاطب حکومت، ادارے، عوام، معاشرہ اور فرد سب ہیں، اور ہرفرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حکم کی تعمیل کرے۔
پانی کو اللہ ربّ العزت کی عطا کردہ نعمتوں اور وسائل میں ایک بنیادی اور نہایت گراں قدر اہمیت حاصل ہے۔ انسانی زندگی بہت حد تک پانی پر منحصر ہے۔ اس کے استعمال میں عدم توازن اور اس میں آلودگی کی وجہ سے انسانی ماحول کو شدیدخطرات کا سامنا ہے۔ قرآن کے نقطۂ نظر سے پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہی نہیں بلکہ زندگی کی بنیاد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاۗءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۰ۭ (الانبیاء۲۱:۳۰) ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔
دوسری جگہ ارشادہے:
وَاللہُ خَلَقَ كُلَّ دَاۗبَّۃٍ مِّنْ مَّاۗءٍ۰ۚ (النور۲۴:۴۵) اللہ نے ہر جان دار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔
پانی کو اس کی فطری حالت پر باقی رکھنا اور اس کے استعمال میں سلیقہ کا لحاظ رکھنا انسانوں کی ذمہ داری ہے، تاکہ اس سے زندگی بخشنے والی صلاحیت ختم نہ ہوجائے۔ پانی میں رہنے والے جاندار بھی زندہ رہ سکیں اور پانی استعمال کرنے والے انسان و حیوان اور نباتات بھی زندگی پاسکیں۔
عبداللہ بن عمروؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعدؓ کے پاس سے گزرے۔ اس وقت وہ وضو کر رہے تھے اور ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کر رہے تھے۔ رسول ؐ اللہ نے فرمایا: یہ کیسی فضول خرچی ہے؟ حضرت سعدؓ نے پوچھا: کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ رسولؐ اللہ نے جواب میں فرمایا: نَعَمْ وَاِنْ کُنْتَ عَلٰی نَھْرٍ جَارٍ ’’ہاں، اگرچہ تم بہتی نہر کے کنارے ہی کیوں نہ وضو کر رہے ہو‘‘۔(سنن ابن ماجہ، ابواب الطہارۃ، باب ماجاء فی القصد فی الوضوء)
خلاصہ یہ ہے کہ پانی کا استعمال بھی سلیقہ سے کیا جائے اور پانی کو آلودگی سے محفوظ بھی کیا جائے۔ اسی لیے رسولؐ اللہ نے پانی میں غلاظت اور کثافت پھیلانے سے بھی منع فرمایا ہے:
جابرؓ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ رَّسُوْلَ اللہِ نَھَی أَنْ یُبَالَ فِی الْمَاءِ الدَّائِمِ، ’’رسولؐ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ ٹھیرے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے‘‘۔ (الصحیح المسلم، کتاب الطہارۃ، باب النہی عن البول فی الماء الراکد)
حیوانات انسان ہی کی طرح اللہ کی مخلوق اور ہمارے ماحول کا حصہ ہیں۔ انسانوں کی ضرورت اور انسانی ماحول کی زینت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری خدمت اور نفع بخش استعمال کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے ان کی نسلوں کا تحفظ اور ان کی دیکھ بھال کرنا انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
وَالْاَنْعَامَ خَلَقَہَا۰ۚ لَكُمْ فِيْہَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْہَا تَاْكُلُوْنَ۵۠ وَلَكُمْ فِيْہَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ۶۠ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْہِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ۰ۭ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۷ۙ وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْہَا وَزِيْنَۃً۰ۭ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۸ (النحل ۱۶:۵-۸) اور جانوروں کو بھی اس نے پیدا کیا۔ ان میں تمھارے لیے پوشاک ہے اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ جب شام کو انھیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو چرانے لے جاتے ہو تو ان میں تمھاری خوب صورتی ہے اور دُور دراز مقامات جہاں تم شدید محنت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے وہ تمھارے بوجھ کو اُٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بے شک تمھارا ربّ شفیق و مہربان ہے اور اسی نے گھوڑے ، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان کی سواری کرو، وہ تمھارے لیے زینت اور رونق بھی ہیں۔ اور وہ پیدا کرتا ہے جس کی تم کو خبر نہیں ہے۔
یہ آیت وائلڈ لائف کنزرویشن یعنی جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے عظیم تحریک فراہم کرتی ہے۔ اس میں جانوروں کی تخلیق، ضرورت، مقصد اور ماحول کی ان سے زینت کے بہت سے گوشے روشن کردیئے گئے ہیں۔ خاص طور پر ایک ایسے معاشرے میں جس کی معیشت میں گلہ بانی مرکزی حیثیت رکھتی ہو، جانوروں کا صبح کو گھر سے نکلنا، چراگاہوں میں جانا اور شام کو واپس آنا ایسا خوش نما منظر پیش کرتا ہے جو انسانوں کی خوشی کا ذریعہ ہے۔
پیڑ پودے، جنگلات اور باغات ماحول کو سازگار بنانے اور موسم کو معتدل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ماحول میں خوش گواری اور خوب صورتی پیدا کرتے ہیں۔ جن علاقوں میں پودے، درخت اور باغات کثرت سے پائے جاتے ہیں وہاں انسان راحت اور مسرت محسوس کرتا ہے، اور جہاں پیڑ پودے نہیں ہوتے وہاں انسان گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے سیروتفریح کے لیے انسان ایسے مقامات کا انتخاب کرتا ہے جہاں کے مناظر دیدہ زیب اور فضا خوش گوار ہو۔ چنانچہ ماحولیات کا تقاضا ہے کہ پیڑپودے برباد نہ کیے جائیں ورنہ موسمی بلائیں دَر آئیں گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ بلاضرورت درختوں کو نہ کاٹا جائے۔ ہرے پیڑ انسان اور حیوانات دونوں کی راحت رسانی کرتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ حدودِ حرم مکہ میں پیڑوں کا کاٹنا اور جانوروں کا مارنا ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپؐ نے فرمایا: جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا اسی طرح مَیں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں ۔ نہ تو یہاں پیڑوں کو کاٹا جائے اور نہ جانوروں کو ہلاک کیا جائے۔ ایندھن کی لکڑیاں اور جانوروں کاچارہ اس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ (نورالدین علی بن احمد السمہودی، وفاء الوفا باخبار المصطفٰی، جلد۱،ص ۱۱۱، پوربند، گجرات)
جنگ میں بہت سی وہ چیزیں اختیار کی جاتی ہیں جو غیراخلاقی اور غیر انسانی ہوتی ہیں تاکہ دشمن پر قابو پایا جاسکے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی دشمن کے درختوں کو بلاضرورت کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔
ماحول میں ہریالی، موسم کی سازگاری اور انسانوں اور جانوروں کی نفع رسانی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ پودوں کو لگانے کی اہمیت کا احساس دلایا۔ حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا ، فَأَكَلَ مِنْهُ إنْسَانٌ أوْ دَابَةٌ ، إلّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (صحيح البخاری، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم - حدیث: ۵۶۷۳) جو مسلمان کوئی پیڑ لگاتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے اور اس پیڑ پودے سے انسان، پرندے یا جانور کھاتے ہیں تو یہ پیڑ لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔
شجرکاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی ہے کہ قیامت تک اس کام کو کرتے رہنے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ رسولؐ اللہ نے فرمایا:
اِنْ قَامَتْ السَّاعَۃُ وَ بِیَدِ اَحَدِکُمْ فَسِیْلَۃً فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لَا یَقُوْمَ حَتّٰی یَغْرِسَھَا فَلْیَفْعَلُ (احمد بن حنبل، المسند، جلد۳، ص ۱۹۱) اگر قیامت کا وقت آجائے اور تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور قیامت کے برپا ہونے سے پہلے وہ اسے لگاسکتا ہو تو اسے ضرور لگا دینا چاہیے۔
شجرکاری کے ذریعے ماحول کا تحفظ کرنے کی اہمیت بارے اس سے بڑی بات نہیں کہی جاسکتی کہ قیامت برپا ہونے میں چند لمحات بھی باقی ہوں تو بھی اگر انسان ایک درخت بھی لگانے کی مہلت بھی پائے تو اسے اس کو لگا دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ حالانکہ جب کسی شخص کو اگلے لمحے دُنیا سے رخصت ہونے کا خیال آتا ہے تو وہ تعمیروترقی کے سارے کام بھول جاتا ہے، اور بس اپنی نجات کے لیے فکرمند ہوتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ مرتے وقت تک ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا بھی آخرت میں سرخرو ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ انقلابی تعلیم آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے انسانیت کو مل سکتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دُنیا کے عام قائدین کی طرح محض لوگوں کو زبانی تعلیم ہی نہیں دیتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو کچھ فرماتے ہیں، خود اس کی صداقت پر عمل کرکے دکھاتے ہیں۔ چنانچہ ہم متعدد مواقع پر دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پیڑ لگاتے ہیں اور وہ پیڑ برگ و بار بھی لاتا ہے۔
مدینہ سے کوئی ۲۰میل کی دُوری پر وادیٔ عقیق ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے لیے ایک چراگاہ بنائی جسے حمی النقیع کہا جاتا ہے۔ اس چراگاہ میں آپؐ نے پیڑپودے لگوائے، سبزیاں لگوائیں۔ کچھ عرصہ بعد اس وادی میں اتنی ہریالی ہوگئی کہ گھوڑے پر سوار ہوکرانسان ان پیڑوں کی چھائوں میں غائب ہوسکتا تھا۔ اس ہریالی کے باعث یہ صرف گھوڑوں کی چراگاہ نہ رہی بلکہ انسانوں کی سیرگاہ بھی بن گئی۔ اس سیرگاہ کی حدودرسولؐ اللہ نے اس طرح مقرر فرمائی کہ ایک شخص کو کھجور کے پیڑ پر چڑھ کر بلند آواز لگانے کو کہا۔ آواز کی گونج جہاں تک سنائی دی وہاں تک اس کی حدود مقرر ہوئیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علمی اور عملی مثالیں ماحولیات کے تحفظ کے سلسلے میں آج کے دانش مندوں ، رفاہی اداروں اور ماہرین علوم کے لیے بصیرت اور مہمیز کا کام دیتی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ آپؐ نے انسان کے اندر ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس پیدا کیا ہے۔ آپؐ نے زمین و آسمان کی نفع بخش چیزوں اور ماحول کی ساری نعمتوں کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو دُنیا میں چاہے حکومت اور معاشرہ بازپُرس نہ کرے مگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور جواب دینا ہوگا۔
قرآن کریم میں ہے: ثُمَّ لَتُسْـَٔــلُنَّ يَـوْمَىِٕذٍ عَنِ النَّعِيْمِ۸ۧ (التکاثر۱۰۲ :۸) ’’روزِقیامت ان نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا‘‘۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی بقدرِ ضرورت استعمال کے اصول پر عمل پیرا ہوکر مکمل حفاظت کی جائے اور اسراف، فسادوبگاڑ سے بچاجائے۔
سیّدنا عمر ؓ بن الخطاب (شہادت:یکم محرم ۲۳ھ)پر اللہ کا یہ خصوصی فضل تھا کہ آپؓ خلافت کی ذمہ داریوں اور نزاکتوں سے بخوبی واقف تھے۔ اس کا حق ادا کرنے میں حددرجہ محتاج اور باریک بین تھے۔ اس معاملے میں وہ سمجھتے تھے کہ ان کا مقام عمر بن خطابؓ کی حیثیت سے نہیں بلکہ خلیفۂ رسولؐ ہونے کی حیثیت سے ہے ۔ آپؓ کے نزدیک اپنی ذات کا کوئی مقام اور وزن نہیں تھا بلکہ اس منصب ِ خلافت کا وزن تھا جس کے لیے اُمت نے آپؓ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔
خلیفہ اللہ کی زمین میں اس کا نائب اور اس کا سایہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سلطانِ عادل کے ذریعے سے وہ کام کروا دیتا ہے جو سلطانِ عادل کی غیرموجودگی میں قرآن بھی سرانجام نہیں دے سکتا۔ اللہ کی نیابت کے لیے فکروعمل کی پاکیزگی، حکمت اور وقار ضروری صفات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ’’جب تک حکمران ظلم نہ کرے اللہ کی نصرت اسے حاصل رہتی ہے اور جوں ہی وہ ظلم کی روش اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے‘‘۔
عمر ؓ بن الخطاب اس قول سے بھی باخبر تھے کہ ’ایک دن کا عدل و انصاف چالیس برس کی عبادت کے برابر ہے‘۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی حضرت عمرؓ کے سامنے رہتا تھا: ’’جو حکمران اپنی رعایا پر ظلم و زیادتی کرے،وہ کبھی انصاف نہیں کرسکتا‘‘(الحاکم)۔فی الحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اقوال حضرت عمرؓ کے سامنے رہتے تھے۔ انھیں آپؐ کا یہ فرمان بھی یاد تھا: ’’سلطان اللہ کی زمین میں اس کا سایہ ہے، اللہ کے بندوں میں سے ہرمظلوم سلطان کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر اگر سلطان عدل کرے تو اس کے لیے اجر ہے اور رعایا پر شکر واجب اور اگر وہ ظلم و ناانصافی کرے تو اس کے لیے عذاب ہے اور ایسی حالت میں رعیت کو صبر کرنا چاہیے‘‘۔
عمر ؓ بن الخطاب بخوبی جانتے تھے کہ مسلمان حکمران کے فرائض کیا ہیں اور انھیں کیسے ادا کیا جاسکتا ہے؟ وہ ان اصولوں کی خاطر زندہ رہے، جو اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے انسانیت کو دیئے ہیں۔ آپؓ اپنی شخصیت کوچنداں اہمیت نہ دیتے تھے بلکہ اصولوں کی بالادستی آپ کا مطمح نظر تھا۔ آپؓ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم خدمت کے لیے چُن لیا تھا اور آپؓ نے اس کا حق بھی ادا کیا۔ آپؓ نے اُمت کے معاملات کو ایسی پختہ اور ناقابلِ شکست بنیادوں پر استوار کر دیا کہ اس کے بعد اصلاح و خیر کا دور دورہ ہو اور فسادوشر کا مکمل خاتمہ ہوجائے۔ جب تک یہ بنیادیں موجود ہیں، انسانیت کبھی گمراہ نہیں ہوسکتی اور بنی نوع آدم کی بھلائی کا کوئی راستہ ان اصولوں کی پیروی کے سوا ممکن نہیں ہے۔
خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد پہلے ہی دن آپ نے لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کردی تھی کہ لوگوں سے حکومت کس طرح معاملہ کرے گی؟ آپ نے کہا: ’’لوگو! وحی کا سلسلہ تو منقطع ہوچکا ہے۔ اب ہم تمھارے ساتھ جو بھی معاملہ کریں گے وہ تمھارے ظاہری حالات اور اعمال کے مطابق ہوگا۔ ظاہراً جس نے خیروبھلائی کا رویہ اپنایا، ہماری طرف سے اسے امن و امان کی ضمانت ہے۔ باطنی حالت اور چھپے ہوئے راز کی ٹوہ ہم نہیں لگائیں گے۔ یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے اور اللہ باطن کے مطابق اور نیتوں کے لحاظ سے بندوں سے حساب لے لے گا۔ اسی طرح جس شخص سے شر اورفساد ظاہر ہوا، ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ اگر وہ کہتا بھی رہے کہ دل اور نیت سے اس کا ارادہ فتنہ و فتور کا نہ تھا تو ہم اس کے ظاہری عمل کے مقابلے میں اس کے اس دعویٰ کو قبول نہ کریں گے‘‘۔
اس بنیادی اصول کے مطابق سیّدنا عمرؓ نے خلافت کی ذمہ داریاں نبھائیں۔
عمر بن الخطابؓ خلیفۂ راشد تھے اور سلطنت میں احکامِ الٰہی کی تنفیذ میں کوئی تساہل گوارا نہ کرتے تھے۔ عام حالات میں بہرحال وہ کسی کو اس کی طبیعت اور مرضی کے خلاف حکم نہ دیا کرتے تھے۔ آپ جبر کی بجائے نصیحت اور ترغیب سے کام لیتے تھے۔ آپ غلاموں پر بھی کوئی چیز بزور ٹھونس دینے کو ناپسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور ملوکیت کے باوجود لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے: ’’دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے‘‘ (البقرہ ۲:۲۵۶)۔اس طرح اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: ’’کیا آپؐ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ لازماً ایمان لے آئیں؟‘‘(یونس ۱۰:۹۹)
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کا حکم دیا ہے اور حق اور باطل کی ان کے سامنے پوری وضاحت کردی ہے مگر انھیں آزادیٔ انتخاب اور آزادیٔ عمل عطا کی ہے۔ ارشادباری ہے: ’’اور کہہ دیجیے کہ حق تمھارے ربّ کی طرف سے ہے۔ پس تم میں سے جو (اپنی آزادمرضی سے)ایمان لانا چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو کفر پر قائم رہنا چاہیے وہ کفر پر رہے‘‘۔(الکہف ۱۸:۲۹)
اللہ تعالیٰ مالک ِ حقیقی ، خالق کائنات اور ربّ العالمین ہونے کے باوجود اپنے دین کے معاملے میں لوگوں پر زبردستی حکم ٹھونسنے کی بجائے انھیں دعوتِ فکر دیتا ہے اور خود فیصلہ کرنے کی حُریت بخشتاہے، تو مخلوق کو یہ حق کیسے حاصل ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی دوسروں پر ٹھونس دیں؟ حضرت عمرؓ کے پاس ایک نصرانی غلام تھا جس کا نام اسق تھا۔ اسق نے خود بیان کیا کہ حضرت عمرؓ مجھ سے کہا کرتے تھے: ’’اے اسق! تم مسلمان ہوجائو تو ہم مسلمانوں کے بعض معاملات میں تمھاری مہارت اور فن سے استفادہ کریں گے‘‘۔ (یعنی اسے کوئی منصب عطا کردیتے) مگر میں انکار کر دیتا تھا۔ اس انکار پر آپ نے کبھی ناراض ہونے یا سرزنش کرنے کا راستہ اختیار نہ کیا‘‘۔
یہ اسلام کی وسیع الظرفی ہے جس میں قول و عمل میں حُریت ِ فکر کا نمونہ نظر آتا ہے۔ حضرت عمرؓ اپنے دور کے سب سے طاقت ور حکمران تھے۔ وہ جو چاہتے کرسکتے تھے مگر اسلام کے سامنے وہ دَم نہ مار سکتے تھے۔اسلام نے ان کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ وہ کسی بے کس انسان کو مجبور نہ کرسکتے تھے کہ وہ اپنی مرضی چھوڑ کر ان کی مرضی کا پابند ہوجائے۔ ایک غلام بھی اپنی مرضی اور حُریت کا یہ مظاہرہ کرتا تھا کہ امیرالمومنینؓ کی بات ماننے سے انکار کردیتا۔ یہ ہے حقیقی آزادی اور مکمل عدل و انصاف۔
عمر بن الخطابؓ تقویٰ میں بھی نمایاں اور ممتاز تھے مگر آپؓ کی شان دیکھیے کہ مسلمانوں کی تربیت کا اہتمام یوں فرمایا کہ حضرت ابی بن کعبؓ سے پوچھا: ’’تقویٰ کیا ہے؟‘‘ انھوں نے جواب دیا: ’’امیرالمومنینؓ کبھی آپ ایسے جنگل میں سے گزرے ہیں جہاں گھنی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور ان کے بیچوں بیچ تنگ پگڈنڈی ہو؟‘‘ امیرالمومنینؓ نے کہا: ’’ہاں، ایسے راستوں سے گزرا ہوں‘‘۔ انھوں نے پوچھا: ’’پھر ایسے راستے سے گزرتے ہوئے آپؓ کیا کرتے ہیں؟‘‘ کہا: ’’دامن سمیٹ لیتا ہوں اور بہت محتاط ہوکر قدم اُٹھاتا ہوں کہ دامن کسی کانٹے سے نہ اُلجھ جائے‘‘۔ حضرت ابیؓ نے کہا: ’’تقویٰ یہی ہے‘‘۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عمرؓ خود تقویٰ کا معنی خوب جانتے تھے بلکہ حضرت ابیؓ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، وہ علم کا مینار تھے اور تقویٰ کا معیار۔ مگر لوگوں کی تربیت کے لیے انھوں نے یہ سوال پوچھا تاکہ وہ تقویٰ کے بارے میں حقیقت سے باخبر ہوجائیں اور یہ بھی جان جائیں کہ سوال پوچھنے سے عزّت نہیں گھٹتی۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کو خشیت کی بدولت ایسی مومنانہ فراست عطا کی تھی جو کبھی انھیں ناکام نہ ہونے دیتی تھی۔ وہ انسانوں کے چہرے اور پیشانیاں دیکھ کر ان کی صفات کا پتہ چلا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابوصفرہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ان کے دس فرزند بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عمرؓ نے ابوصفرہ کے لڑکوں کو غور سے دیکھا اور ان میں سے سب سے چھوٹے لڑکے مہلب کے بارے میں کہا: ’’ابوصفرہ تمھارا یہ لڑکا سردار ہوگا۔ یہ اپنے اندر جوہرِ قابل رکھتا ہے‘‘۔ مہلب اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا مہلب کیسی قابل شخصیت بن کر اُبھرا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مشاہیر اسلام میں مہلب بن ابی صفرہ کا مرتبہ کتنا عظیم ہے۔
اس فراست کی بدولت حضرت عمرؓ انسانوں کی مشکلات و مسائل کے حل کرنے میں ہردم سرگرمِ عمل رہتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن یزید نے اپنے باپ کی زبانی روایت بیان کی ہے کہ وہ حضرت عمرؓ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے کہ کیا موزوں پر مسح جائز ہے؟ آپ نے ہماری بات سنی تو کوئی جواب نہ دیا بلکہ اُٹھے اور پیشاب کرنے چلے گئے۔ واپس آئے تو وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کرلیا۔ ہم نے کہا کہ آپ سے ہم نے سوال پوچھا تھا۔ آپ نے جواب دیا: ’’میں نے تمھارے سوال کا عملی جواب دے دیا ہے اور اس وقت میں تمھاری خاطر ہی اُٹھ کر گیا تھا‘‘۔
بعض لوگ کسی چیز کے متعلق جانتے نہیں مگر سوال پوچھنے سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سوال پوچھنے سے انسان کی شان نہیں گھٹتی۔ وہ لوگ کتنے عظیم اور خوش بخت ہیں جو لوگوں کے سوال کرنے سے قبل ہی ان کی حاجات پوری کردیتے ہیں۔
عمر ؓ بن الخطاب کی فراست ِ مومنانہ انھیں اُمورِ مملکت چلانے میں بھی مدددیا کرتی تھی۔ اپنے عمال کے بارے میں صدقِ نظر اور ژرف نگاہی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمانؓ سے پوچھا: ’’کیا میرے عمال میں کوئی منافق ہے؟‘‘ حضرت حذیفہؓ کو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بتا دیا تھا، لہٰذا وہ جانتے تھے۔ انھوں نے جواب دیا: ’’ہاں ایک ہے‘‘۔ پوچھا:’’کون ہے؟‘‘ تو انھوں نے جواب دیا:’’میں اس کا نام ہرگز نہ لوں گا‘‘ (چونکہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لینے سے منع کیا ہوا تھا، اس لیے حضرت حذیفہؓ کسی منافق کو نامزد نہ کیا کرتے تھے)۔ حضرت حذیفہؓ کہتے تھے کہ حضرت عمرؓ نے اس عامل کو معزول کر دیا۔ گویا کہ انھیں علم ہوگیا تھا‘‘۔ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا: ’’مومن کی فراست سے بچا کرو۔ بے شک وہ اللہ کی دی ہوئی روشنی سے دیکھتا ہے‘‘۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادِ ربانی بھی ہے: ’’بے شک ان واقعات میں صاحب ِ فراست لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں‘‘۔(الحجر۱۵: ۷۵)
حضرت انسؓ بن مالک سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو لوگوں کی حقیقت کو اپنی فراست سے پاجاتے ہیں‘‘۔
عمر ؓ بن الخطاب ان بچوں کے بارے میں جنھیں پیدائش کے بعد نظرانداز کردیا جاتا تھا اور جن کے بارے میں کوئی پتہ نہ چلتا تھا کہ ان کے والدین کون ہیں یا جن کے والدین فوت ہوجاتے اور ان کا کوئی رشتہ دار نہ ہوتا تھا، بڑے فکرمند رہتے تھے۔ ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان پر سرکاری خزانے سے اخراجات اُٹھتے تھے اور ان کا وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا۔ آپ ان کے بارے میں اچھے سلوک اور ان کی دیکھ بھال کی ہمیشہ نصیحت کیا کرتے تھے۔
عمر بن الخطابؓ ، اہل ایمان کے لیے دینی و دُنیوی ہرمعاملے میں آسانی تلاش کرتے تھے اور تنگی سے انھیں بچانے کی فکر کیا کرتے تھے۔ لوگ اگر اپنے لیے مشکل راستہ ڈھونڈتے تو بھی آپ ؓ انھیں آسانی اور فراخی کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ بشر بن فخیف سے مروی ہے کہ وہ حضرت عمرؓ کے پاس گئے اور کہا: ’’میں آپ کی بیعت کرتا ہوں کہ ہرمعاملے میں جسے مَیں پسند کرتا ہوں اور جسے ناپسند کرتا ہوں، آپ کی اطاعت کروں گا‘‘۔ آپؓ نے فرمایا: ’’ایسا نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ میں حسب ِ استطاعت آپ کی اطاعت کروں گا‘‘۔
عمر ؓ بن الخطاب خود سخت کوش اور جفاکش تھے، مگر لوگوں کے لیے آسانی چاہتے تھے۔ اپنی سخت کوشی کا ڈھنڈورا کبھی نہ پیٹتے تھے۔ جو لوگ سستی شہرت کی خاطر بلندبانگ دعوے کرتے ہیں، وہ ڈھول کا پول ثابت ہوتے ہیں اور وقت آنے پر ان کا راز کھل جاتا ہے کہ وہ کتنے بودے اور ناکارہ ہیں۔
عمر بن الخطابؓکی خلافت ہر پہلو سے مثالی تھی۔ ہرمعاملے میں خلیفۂ راشد اپنے آپ کو جواب دہ اور ذمہ دار گردانتے تھے اور رعایا کی ہرضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ نظمِ حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم تھا، ادارے منظم تھے۔مواصلات کا نظام بہترین تھا اورراستے محفوظ اور بہترین انداز میں بنائے گئے تھے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں سڑکیں بنتی ہیں تو اگلے دن ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، جب کہ اس دور میں سڑکیں بنتی تھیں تو مدتوں ان میں خرابی پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تھا۔ مصر اور مدینہ کا فاصلہ بے پناہ تھا، مگر حضرت عمرؓ کے ذہن رسا نے یہ فاصلہ پاٹ دیا۔ ان کے دورِ حکومت میں مصر سے غلہ لانے کے لیے بحری جہاز استعمال کیے گئے۔ جہازوں کے ذریعے غلہ جار کی بندرگاہ تک لایا جاتا تھا۔ وہاں سے پھر اُونٹوں پر لاد کر محفوظ سڑک کے ذریعے ایک دن اور ایک رات میں کاررواں مدینہ پہنچ جاتا تھا۔ جاربحراحمر پر بندرگاہ تھی۔ حضرت عمرؓسے قبل مصر سے حجاز تک سارا سفر صحرا اور خشکی کے ذریعے طے ہوتا تھا جو بڑا پُرصعوبت تھا اور اس میں کافی مدت بھی لگتی تھی۔
عمر ؓ بن الخطاب کے دور میں آپؓ کا گھر ہرشخص کے لیے جائے قرار تھا۔ حاجت مندوں کے لیے آپ کا دروازہ ہروقت کھلا رہتا تھا۔ جو شخص آتا اس کا استقبال ہوتا تھا اور اس کی دادرسی کی جاتی تھی۔ کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ تھی۔ ایک اصول تھا جس سے ہرخاص و عام واقف تھا کہ جو زیادہ نیک اور متقی تھا، وہ زیادہ معزز و محترم سمجھا جاتا تھا۔ جس نے اعمالِ خیر اور جہادِ اسلامی میں زیادہ خدمات سرانجام دی تھیں، وہ دوسروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہ تھا جس سے لوگوں کا مرتبہ متعین کیا جاتا۔
جب حق داروں کو ان کا حق نہ ملے اور صاحب ِ استحقاق کے مقابلے میں بااثر لوگوں کو ترجیح دی جانے لگے تو فساد پھیل جانا فطری امر ہے۔ حکمران اگر یہ اصول پیش نظر رکھیں کہ جس شخص نے اُمت کے لیے زیادہ قابلِ قدر خدمات سرانجام دی ہیں، اس کی عزّت افزائی اور قدر کی جائے، تو اس سے بہت صحت مند رجحان پروان چڑھتا ہے۔ لوگ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیاں بُرائیوں پر غالب آجاتی ہیں۔
جرید بن حازم بن حسن سے مروی ہے: ’’کچھ لوگ امیرالمومنین عمرؓ بن خطاب کے دروازے پر آئے۔ ان میں اصحابِ بدر بھی تھے اور شیوخِ قریش بھی۔ ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اصحابِ بدر میں سے صہیبؓ، خبابؓ، عمارؓ اور بلالؓ کو اندر آنے کی اجازت مل گئی، جب کہ ابوسفیانؓ، حارثؓ بن ہشام اور سہیلؓ بن عمرو کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ یہ سب بزرگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔
اس صورتِ حال کو دیکھ کر ابوسفیان ؓ نے کہا: ’’آج کے دن سے زیادہ میں نے اپنی بے قدری کبھی نہ دیکھی تھی۔ رؤسائے قریش باہر بیٹھے ہیں اور غلاموں کو اندر بلا لیا گیا ہے‘‘۔ یہ سن کر سہیلؓ بن عمرو نے کہا اور سہیلؓ بہت عقل مند اور متقی تھے: ’’اے سردارانِ قریش! میں نے تمھارے چہروں پرنا راضی کے آثار دیکھ لیے ہیں۔ اگر غصہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر کرو۔ سب لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی اور تمھیں بھی مخاطب کیا گیا تھا۔ وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے اور تم پیچھے رہ گئے۔ تمھیں اس دروازے سے ان کا پہلے داخل ہونا ناگوار گزر رہا ہے۔ خدا کی قسم! یہ تو کوئی بات نہیں۔ وہ تو اپنے درجات کی بلندی میں تم سے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر تم اس کا احساس کرو تو اپنی محرومی پر کف ِ افسوس ملتے رہ جائو: ’’اے لوگو! یہ راہِ خدا میں جہاد اور سبقت ِ اسلام کی وجہ سے تم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب تمھارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تلافی ٔ مافات کرسکو اور وہ جہاد کا راستہ ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ تمھیں شہادت کا رُتبہ عطا کرکے تمھارے درجات بلندفرما دے‘‘۔
حضرت سہیلؓ اس کے بعد اسلامی لشکر کے ساتھ شام میں جاشامل ہوئے اور میدانِ جہاد میں شہادت پائی۔ حسن ان کے بارے میں مندرجہ بالا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے: ’’خدا کی قسم! سہیلؓ نے سچ کہا جو بندہ اللہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ جائے، اس کے برابر دعوت کو ٹھکرا دینے والا کیسے ہوسکتا ہے؟‘‘
عمر بن الخطابؓ بطورِ حاکم اپنے فرائض کی ادائیگی میں سرگرمِ عمل رہتے تھے۔ بہت سے نیک نفس حکمران اور بھی ہیں جو اپنے واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرتے تھے اور آج بھی اگر کوئی حکمران سنجیدگی سے کمرہت باندھ لے تو یہ کام کرسکتا ہے، مگر حضرت عمرؓ کا اس معاملے میں کمال یہ ہے کہ وہ ان فرائض کی ادائیگی میں لطف محسوس کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ عبادت کا حصہ تھا۔ رعایا کے لیے جذبات، محبت اور نیکی کے کاموں کے لیے ہمیشہ کمربستہ رہنا ان کی شان تھی۔ انھوں نے خلافت کا بھاری بوجھ جس کے اُٹھانے سے پہاڑ عاجز تھے، اُٹھایا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ اس بوجھ کے باوجود وہ دوسروں کا بوجھ کم کرنے اور اپنے اُوپر زیادہ بوجھ لادنے کی فکر میں رہتے تھے۔ حق داروں کو ان کے پاس پہنچ کر حق ادا کیا کرتے تھے۔ وہ راتوں کو گلی کوچوں میں گھوم پھر کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے کندھوں پر بوجھ اُٹھایا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ حضرت عمرؓ خود رجسٹر اُٹھائے بنوخزاعہ کے پاس قدید پہنچے اور ان کے وظیفے انھیں دیتے ہوئے فرمایا: ’’یہ تمھارا حق ہے۔ تمھیں اپنا یہ حق وصول کرکے اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنی خوشی مجھے ادا کرکے ہورہی ہے۔ تم لوگ میری تعریف نہ کرو۔ میں نے کیا تیر مارا ہے، بس اپنا فرض ادا کیا ہے‘‘۔
یہ عظمت ِ کردار کہاں مل سکتی ہے؟ سربراہِ مملکت اپنی پیٹھ پر سامان لادے لوگوں تک پہنچتا ہے اور نہ کوئی اعلان ہوتا ہے نہ تشہیر، نہ سپاسنامہ، نہ قصیدہ خوانی! وہ اللہ کے سامنے حاضری اور جواب دہی کے احساس سے مالا مال تھے۔ انھیں معلوم تھا کہ بندوں کے معاملے میں اللہ نے ان پر کیا کچھ واجب کر رکھا ہے۔
آج صورتِ حال یہ ہے کہ حق دار بے چارے جوتیاں چٹخاتے رہتے ہیں اور پوری زندگی اپنے جائز حقوق کے حصول اور دادرسی کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ کبھی کوئی حق مل جاتا ہے ورنہ اکثر ان لوگوں کے حصے میں حرماں نصیبی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حکومتی اداروں کو چلانے والوں کے دلوں میں اگر خوفِ خدا پیدا ہوجائے تو ہر حق دار کو اس کا حق مل سکتا ہے مگر ایسا نہیں ہوتا۔
عمر بن الخطابؓسخت گیر بھی تھے مگر اس کے ساتھ نرم دل بھی تھے۔ جہاں سختی کی ضرورت ہوتی تھی وہاں آپ سے زیادہ سخت کوئی نہ تھا اور جہاں نرمی کا موقع محل ہوتا وہاں آپؓ کی رقت ِ قلب بے مثال ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان جوڑا زنامیں پکڑا گیا۔ دونوں غیرشادی شدہ تھے۔ آپ نے لڑکے اور لڑکی دونوں پر حد ِ تازیانہ جاری کی اور اس میں بالکل نرمی نہ دکھائی۔ حدجاری ہوچکی تو آپؓ نے ان دونوں سے کہا: ’’آپس میں شادی کرلیں مگر لڑکے نے انکار کر دیا۔ آپؓ نے اس کے انکار پر نہ بُرا مانا اور نہ اسے کوئی دھمکی دی۔ حدود اللہ کا قیام اللہ کا حق ہے،جس میں کوئی کمی بیشی قابلِ قبول نہیں اور افراد کی شخصی آزادی ان کا بنیادی حق ہے جس پر قدغن نہیں لگائی جاسکتی۔
آج بُرائی پھیل چکی ہے اور اس پر کوئی پکڑنے والا نہیں۔ ان حالات میں مسلمان لڑکیوں کو اپنی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے خود بیدار اور محتاط رہنا چاہیے۔ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے اور اس کے حملے ہروقت جاری رہتے ہیں۔ شیاطین الجن اور شیاطین الانس کے غول کے غول پھرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی کی عزّ ت اور شرف کا کوئی تقدس اور حُرمت نہیں ہے۔ انھیں یہ بات یاد ہی نہ رہی کہ ’جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ‘کا اصول اٹل ہے۔ وہ ذاتِ بابرکات جو ہرشخص کے ہرعمل سے باخبر ہے، اس کے سامنے حاضری کے دن سب کو اپنے اپنے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور حی و قیوم ہے۔
عمر بن الخطابؓاپنی رعایا کے ہرمعاملے میں دلچسپی لیتے تھے، جس طرح والدین اپنی اولاد کے جملہ اُمور کی نگرانی کرتے ہیں۔ آپؓ اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ لوگ اپنے وقت کا استعمال کس طرح کرتے تھے؟ کبھی آپؓ انھیں پیار محبت سے سمجھاتے اور کبھی درہ لہرا کر انھیں تاکید کرتے تھے۔ رات کو دیر تک جاگتے رہنا آپؓ کو ناپسند تھا۔ آپؓ لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ جلدسونے کی عادت ڈالیں تاکہ جلد اُٹھ سکیں اور اگر توفیق مل جائے تو تہجد کی سعادت حاصل کرسکیں۔ آپؓ کی خلافت میں فضول کاموں اور عبث باتوں کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ آپؓ جانتے تھے کہ وقت بہت قیمتی متاع ہے اور کام بے شمار ہیں جن کی تکمیل کے لیے وقت کا ایک ایک لمحہ احتیاط سے استعمال میں لانا چاہیے۔ اگر لوگ عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانی سننے سنانے کے لیے بیٹھ جاتے تو حضرت عمرؓ کو سخت ناگوار گزرتا۔ آپؓ انھیں سرزنش فرماتے۔
اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات میں بڑی حکمت اور اپنے بندوں کے مفاد کو ملحوظ رکھا ہے۔ وہ بندوں کے نفع و نقصان کو خوب جانتا ہے۔ اس نے دن کو کام کاج اور تلاشِ معاش کے لیے اور رات کو آرام و راحت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رات کو جلد ہی سوجانے والا شخص اگلے دن اپنے کاموں میں پوری چستی اور نشاط کے ساتھ علی الصبح مشغول ہوجاتا ہے۔ نہ اس پر سُستی اور کاہلی کا غلبہ ہوتا ہے اور نہ وہ اُ ونگھتا ہے۔ راتوں کو لمبی محفلیں جما کر بیٹھے رہنا انسان کے لیے ہرلحاظ سے نقصان دہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپؐ عشاء کی نماز سے قبل سونے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔
عمر ؓ بن الخطاب نے جب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ رات کو جلد سو جایا کریں تو ان کے پیش نظر یہی حدیث ِ رسولؐ اور حکمِ ربانی جو سورئہ مزمل کی آیت ۶ میں دیا گیا ہے، رہا ہوگا۔ اس آیت میں اللہ کا ارشاد ہے: ’’بے شک (پچھلی) رات کو اُٹھنا (اور عبادت میں مصروف ہو جانا) نفس امّارہ کو کچلنے اور صحیح اور سچّی بات کہنے کی عادت ڈالنے کے لیے بہت مفید ہے‘‘۔
رات کی خاموشی اور تنہائی میں اللہ کی اطاعت وعبادت کا جو لطف آتا ہے وہ ناقابلِ بیان ہے۔ سکونِ قلب حاصل ہوتا ہے۔ خاموش فضا میں دل و دماغ، آنکھیں اور کان، سوچ اور دھڑکن، ہرچیز اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ رات کی سیاہ زُلفیں خشوع و خضوع سے دل کو بھر دیتی ہیں اور رکوع و سجود، قیام و قعود، دُعا و مناجات، ہرمرحلہ کیف و سُرور سے مالا مال کردیتا ہے۔
عمر ؓ بن الخطاب نوجوانوں کے اندر قوت و صحت اور زندگی و مردانگی کے آثار دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلم نوجوان ظاہر و باطن ہر لحاظ سے اسلام کی شوکت و قوت کا مظہر بن جائیں۔ ایک نوجوان کو مریل چال چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا: ’’کیا تم بیمار ہو؟‘‘۔ اس نے کہا: نہیں امیرالمومنینؓ، میں بالکل تندرست ہوں‘‘۔ اس پر آپؓ نے درہ لہرایا اور فرمایا: ’’پھر یہ مردنی تم پر کیوں چھائی ہوئی ہے، جواں مردوں کی طرح چلو‘‘۔
عمر ؓ بن الخطاب اپنی رعایا کے ہرخاص و عام کو تذکیر و نصیحت کرتے رہتے تھے۔ اُمہات المومنینؓ کا مقام و مرتبہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ حضرت عمرؓ نے نماز پڑھاتے ہوئے سورئہ اَحزاب کی تلاوت کی اوران آیات پر پہنچے جن میں ربّ العزت نے اَزواجِ مطہراتؓ کو یاالنساء النبی کہہ کر خطاب کیا ہے تو آواز بلند ہوگئی۔ نماز کے بعد لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ اُمہات المومنینؓ کو وہ عہد یاد دلانا مقصود تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی طور پر نازل فرمایا تھا۔ سچّی بات یہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں تذکیر اور یاد دہانی سے بے نیاز نہیں ہوسکتے۔ تذکیر کا اہلِ ایمان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: ’’نصیحت کیا کرو، بے شک نصیحت سے اہل ایمان کو نفع پہنچتا ہے‘‘۔(الذاریات ۵۱:۵۵)
آج مسلمانوں ، خصوصاً مسلمان حکمرانوں اور اسلام میں بدقسمتی سے بہت بُعد پیدا ہوگیا ہے۔ ان حالات میں عمر بن الخطابؓ کے طرزِ خلافت کے ان پہلوئوں کا تذکرہ مسلم معاشرے کی اصلاح و ترقی کے لیے بنیادی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ فَہَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ۴۰ (القمر۵۴:۴۰) ’’پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا‘‘۔
ہندستان کے [برطانوی غلامی میں] پریشان کن حالات میں ایک ایسی اصولی اسلامی دعوت ظہور پذیر ہوئی، جو قومی تعصبات اور جغرافیائی نعروں، نسل پرستی کے میلانات اور مغربیت کے تصورات سے پاک تھی۔ ایک سچّی اور حقیقی دعوت، جو کتاب اللہ کے چشمۂ صافی سے پھوٹنے والی، سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابِ رسولؐ کے جہاد زندگانی سے ماخوذ تھی۔ دینِ مبین کی طرف رجوع کرنے اور اس سے وابستگی کی وہ ہمہ گیر دعوت کہ انسان کو زندگی کے مختلف پہلوؤں اور شعبوں میں جو بھی مسائل و مشکلات پیش آئیں، وہ ان کا حل اسلام ہی میں تلاش کرے۔
یہ تحریک اقامت ِدین اور دینِ صحیح کے ان روشن امتیازی نشانات کو زندہ وتابندہ کرنے کی دعوت کی صورت میں سامنے آئی۔ اسلام کی صاف شفاف فکر میں در آنے والی مشرقی خرافات اور مغربی اوہام نے مسلم معاشروں میں ٹیڑھے ترچھے راستے اور خودساختہ طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ گذشتہ صدیوں کے دوران عالم اسلام میں رفتہ رفتہ پروان چڑھتے انحطاط، فکروعمل پر مسلط جمود، اور بے عملی سے وابستہ اندھی تقلید پر مشتمل بدعات کے خاتمے کی یہ دعوت، ۱۹۳۰ء کے عشرے کے تھوڑی ہی دیر بعد ظہور میں آئی۔ اُس وقت، جب برصغیر میں مسلم قومیت اور متحدہ قومیت کی تحریکیں برسرِپیکار تھیں۔ ہر مخلص مسلمان ورطۂ حیرت میں تھا کہ وہ ان حالات میں کیا کرے؟ اس پریشان کن صورت حال میں اُن کو حیرت سے نکالنے اور ہدایت وحق کے نور سے منور ہونے کی خوش خبری پر مشتمل یہ دعوت ظہور پذیر ہوئی۔ اسی دعوت نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ جہدوعمل کے ایک واضح لائحہ عمل اور صاف سیدھے طریق کو ان کے سامنے روشن کرے۔
اس دعوت کو برپا کرنے والوں کا اوّلین ہدف، نظرئیے اور تصور کی درستی، حقیقت دین کے بیان، عقیدۂ توحید کو گم کرنے والے مشرکانہ تصورات کی تطہیر اور اسلام کی صاف ستھری تعلیمات کو وقت گزرنے کے ساتھ دَر آنے والی آلودگیوں سے پاک کرنا تھا۔
چونکہ یہ کام اسلام کے حقیقی مفہوم، اسلام کے مطلوب اغراض و اہداف اور واضح اصول و مبادی پر مشتمل ہے۔ اس لیے اس نے انفرادی اور اجتماعی تربیت، معاشرتی اصلاح اور نظامِ حکومت کو اسلام کے انھی تصورات کے زیر سایہ انجام دینا طے کیا۔ بدقسمتی سے ماضی میں باطل نظریات، گمراہ کن افکار اور جمود کی گرد میں اسلام کی حقیقی فکر دب کر رہ گئی تھی، اور یہ بات کسی صاحب ِدانش سے قطعاً مخفی نہیں ہے۔
اسلام ___ جیسا کہ کتاب اللہ اور سنت رسولؐ اللہ سے سمجھ میں آتا ہے، خاص طور پر اور جیسا کہ اس دعوت کے اٹھانے والوں نے اپنی تصنیفات اور رسائل و اخبارات میں بیان کیا ہے، یہی وہ دین ہے جس کے سوا کسی اور دین کو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے قبول نہیں کرے گا:
وَمَنْ يَّبْتَـغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْہُ۰ۚ وَھُوَفِي الْاٰخِرَۃِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۸۵ (اٰل عمرٰن۳:۸۵)اور اس فرماں برداری (اسلام) کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، اس کا وہ طریقہ ہرگزقبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔
یعنی دینِ اسلام ہی انسانی زندگی میں فکرو عمل کے لیے واحد، حقیقی اور موزوںطریقہ ہے، اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ انسانی زندگی کے لیے اسلام کی اس مناسبت و موزونیت پر اس بات کا اضافہ بھی کر لیجیے کہ یہی انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں اور پہلوئوں کا احاطہ کرنے والا جامع لائحہ عمل ہے۔ یہ کسی ایک خطۂ زمین کے لیے کچھ، اور دوسرے قطعۂ ارض کے لیے کچھ اور نہیں، ایک زمانے کے لیے کچھ، اور دوسرے زمانے کے لیے کچھ اور نہیں، ایک قوم کے لیے کچھ، اور دوسری کے لیے کچھ مختلف نہیں ہے۔جیسا کہ ارشاد خداوندی سے ظاہر ہے: اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللہِ الْاِسْلَامُ ۰ۣ (اٰل عمرٰن ۳:۱۹)’’اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے‘‘۔
دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ، تمام ترانسانی زندگی کا احاطہ کرنے اور ہر دور کے مسائل وضروریات کی کفایت کرنے والا، واحد صحیح دین اسلام ہے۔ مغربی تہذیب اور افکار کی چمک سے متاثر ہو جانے والے بعض فریب خوردہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بندے اور اللہ کے درمیان محض ایک انفرادی اور ذاتی معاملہ ہے، اس کا معاشرے اور نظامِ حکومت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مفروضہ بے خبری یا دانستہ کج بحثی پر مبنی ہے۔
یہ امر واضح ہے کہ اسلام، عیسائیت یا یہودیت اور بدھ مت وغیرہ کی طرح چند متعین رسوم اور معلوم طریقوں کی مانند مذہب نہیں ہے، جنھیں بندہ اپنے اوقات کے محدود حصے میں اپنے رب کے سامنے ادا کرتا ہے اور معاملات زندگی میں اسی رب کی مرضی سے بالکل آزاد و بے مہار ہو جاتا ہے، اور پھر جیسا چاہتا ہے کرتا پھرتاہے اور اپنے اوپر کوئی پابندی نہیں قبول کرتا۔ اس کے مقابلے میں اسلام، انسان کی مکمل انفرادی اوراجتماعی زندگی کا نظام ہے۔ وہ انسان کو مکمل طور پر زندگی کی ارفع و اعلیٰ قدریں اپنانے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ انسانوں کو آخرت کی جواب دہی کا احساس دلا کر سیدھے راستے کی پیروی کی طرف بلاتا ہے۔
ان کے سامنے زندگی کے ہر جزو، ہر پہلو، ہر گوشے اور ہر شعبے میں مثالی طریقے روشن کرتا ہے۔ اسلام کی یہ رہنمائی فرد سے لے کر خاندان تک، سیاست سے لے کر شہریت تک، جنگ سے لے کر صلح و امن تک کے تمام امور اور مسائل میں یکساں اور مثالی ہے۔
یہی اسلام کی بے آمیز اور خالص فکر ہے اور یہی دینِ اسلام کا حقیقی مفہوم ہے۔ اسلام کسی سطحی سوچ اور بے سمت عقیدے کا نام نہیں ہے۔ یہ وہ عملی طریق زندگی ہے جورسولِ خدا، حضرت محمد بن عبدالله صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جس کی پیروی واتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور جس کے واضح خطوط اور روشن اصول و ضوابط کے نفاذ و تنفیذ کی ہدایت دی گئی ہے۔
یہی ہے وہ بندگی جس کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی، اور یہی فریضہ اقامت دین کا مفہوم ہے، جس کا حکم اللہ تعالی نے اپنے انبیا علیہم السلام کو دیا، اور پھر تمام اہل ایمان کو بھی اس کی پیروی کی ہدایت کی۔ جیسا کہ ه قادرِ مطلق نے فرمایا:
شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِہٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِہٖٓ اِبْرٰہِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْہِ۰ۭ (الشورٰی۴۲:۱۳) اُس نے تمھارے لیے دِین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوحؑ کو دیا تھا، اور جسے (اے محمدؐ) اب تمھاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جائو۔
اس لیے یہ بات واضح ہے کہ اسلام کس ارفع و اعلیٰ عقیدے اور جامع نظامِ زندگی کی دعوت دیتا ہے اور یہ بھی کہ اسلام کا وہ حقیقی پیغام کیا ہے جو وہ روئے زمین پر پھیلانا اور تمام خطوں اور تمام انسانوں میں عام کرنا چاہتا ہے۔ اُمت مسلمہ تو برپا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ وہ اس پیغام کو دنیا بھر میں پہنچائے، اس عقیدے کو پھیلائے اور اس نظام کو عمل میں لاکر دکھائے:
كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّۃٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللہِ۰ۭ (اٰل عمرٰن ۳:۱۱۰) اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔
تاریخ نے ان زندہ ه مشاہدات کو اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے، جو زبانِ حال سے اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ پہلے دور میں امت نے اپنے اس فریضے کی بہترین طریقے سے ادائیگی کی تھی، جس میں صحابہؓ و تابعینؒ اور مابعد کے دورِ سلف صالحینؒ شامل تھے۔ مگر دل جس خیال سے رنجیدہ اور غم زدہ ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بعد کے ادوار میں اُمت اس فریضے کی ادائیگی سے غافل ہوگئی اور اب تک غافل چلی آرہی ہے۔ اس فریضے کی انجام دہی میں خطرناک حد تک گناہ کی مرتکب ہے جس فریضے کی ادائیگی کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈالی گئی تھی ___ ان حالات میں اس سے زیادہ ضرورت مند کون سی امت اور قوم ہو سکتی ہے کہ اس میں ایک خالص اسلامی تحریک برپا ہو، جو د عوتِ دین کا کام اَز سرِ نو انجام دے اور نئے سرے سے اپنے مقصودو منزل کی طرف عازمِ سفر ہو۔ جو اپنے قول وفعل کے ذریعے حق کی شہادت دے اور اللہ کے خالص دین کو انسانیت کے سامنے پیش کرے۔ دنیا وآخرت کی خیر وفلاح لوگوں کے سامنے رکھے اور اس کا جامع اور مکمل عالمی نظام اُن کے سامنے پیش کرے ___ وہ دین جودنیاوی و اُخروی کامیابیوں اور سعادتوں کا ضامن ہے، جو جلد حاصل ہونے والے فائدے کی ضمانت بھی دیتا ہے اور دیر سے ملنے والے نفع کی نوید بھی سناتا ہے۔
سعادت مندی اور کامیابی و کامرانی کا یہ کام واضح دلائل، روشن براہین،جدید اسالیب، مؤثر حکیمانہ طریقوں اور دلوں کی گہرائیوں میں اتر جانے والے طرزِ کلام کے ذریعے ہوگا۔ ایسا طرزِ کلام جو اس دور میں عوام کے فہم وشعور اور اندازِ غوروفکر سے ہم آہنگ ہو اور سننے پڑھنے والوں کے طبائع اور زمانے کے ذوق سے مناسبت رکھتا ہو، کیونکہ ہر دور اور زمانے میں حالات اور اسالیب بدلتے رہتے ہیں ۔لہٰذا بنیادی اصولوں پر پختگی سے قائم رہتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کرنے کے انداز بدلنے ضروری ہیں۔ تاکہ مؤثر طریقے سے ابلاغ ہو، اور حق بات بڑے پیمانے پر ہر خاص و عام تک پہنچے۔
اس دعوت کے خدوخال دعوت کے داعی سیّدابوالاعلیٰ مودودیؒ نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے تھے، جو حسب ذیل ہیں:
اگر ہم اس دعوتِ دین، حق اور اسلام کی خالص دعوت اور اس کے اہداف و مقاصد کو مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو ان کو تین نکات کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں:
۱- یہ کہ ہم بندگانِ خدا کو بالعموم اور جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو بالخصوص اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں۔
۲- یہ کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرنے یا اس کو ماننے کا دعویٰ یا اظہار کرے، اس کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے منافقت اور تناقض (دو رنگی)کو خارج کر دے اور جب وہ مسلمان ہے، یا بنا ہے، تو مخلص مسلمان بنے، اور اسلام کے رنگ میں رنگ کر یک رنگ ہو جائے۔
۳- یہ کہ زندگی کا نظام جو آج باطل پرستوں اور فُساق و فُجار کی راہ نمائی اور قیادت و فرماںروائی میں چل رہا ہے، اور معاملاتِ دُنیا کے نظام کی زمامِ کار، جو خدا کے باغیوں کے ہاتھ میں آگئی ہے۔ ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ اسے بدلا جائے اور راہ نمائی وامامت، نظری اور عملی دونوں حیثیتوں سے مومنین و صالحین کے ہاتھ میں منتقل ہو۔
یہ تینوں نکات اگرچہ اپنی جگہ بالکل واضح ہیں، لیکن ایک مدت دراز سے ان پر غفلتوں اور غلط فہمیوں کے پردے پڑے رہے ہیں۔ اس لیے بدقسمتی سے آج غیرمسلموں کے سامنے ہی نہیں، جن کو اسلام کی دعوت اور تعلیم سے آگاہی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے سامنے بھی ان کی تشریح کی ضرورت پیش آگئی ہے۔ لہٰذا ہم یہاں ان کی وضاحت کیے دیتے ہیں:
اللہ کی بندگی سے مراد، جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی بندگی کا اقرار کر لے اور پھر عملی زندگی میں اس سے مطلقاً آزاد رہے، جیسا کہ وہ جاہلیت کی زندگی میں تھا۔ پھر اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا عقیدہ رکھے، اسے ہرجان دار کا رازق مانے، تمام مخلوقات میں اس کی عبادت کا حق تسلیم کرے، لیکن دنیاوی زندگی کے امور و مسائل میں اس کی کوئی حکمرانی تسلیم نہ کرے۔ اسی طرح بندگی کا یہ مفہوم بھی نہیں ہے کہ زندگی کو دو حصوں میں بانٹ لیا جائے۔ ایک حصہ مذہبی اور دینی امور سے متعلق ہو، اور دوسرا دنیا کے امور و معاملات سے متعلق ہو۔ بندگی و عبادت رائج تصور کے مطابق صرف عقائد وعبادات اور اُن مسائل تک محدود ہو، جو انفرادی زندگی اور شخصی حالات سے متعلق ہوں۔ رہی دُنیوی زندگی اور اس کے اُمور و مسائل جو تمدن و معاشرت، سیاست و معیشت، علوم و فنون اور آداب و اخلاق وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اُن میں اللہ کی حکمرانی کو نہ مانا جائے اور نہ اس کے اوامر و احکام کو یہاں نافذ کیا جائے۔ ان میں بندہ بالکل آزاد ہو، جو چاہے کرے، اور حکومت و سلطنت وغیرہ میں جیسا چاہے نظام وضع کرے۔
چونکہ دین ایک ہی ہے جو کبھی بدلا نہیں، اور کتاب بھی ایک ہی ہے، جس میں کہیں سے بھی باطل داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس دعوت کے داعی اس ملک میں بھی اور تمام اقصائے عالم میں بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ بندگی کے مذکورہ سارے مفاہیم بنیادی طورپر باطل ہیں۔ لہٰذا، وہ کفر وجاہلیت اور شرک و اباحیت کے ان نظاموں کا جڑ سے خاتمہ چاہتے ہیں۔ کیونکہ بندگی کے اس ناقص اور ترمیم شدہ مفہوم اور ان کی من مانی تعبیرات نے اسلام کا حقیقی چہرہ مسخ کر رکھا ہے اور دین کا حقیقی تصوّر چھپا کر رکھ دیا ہے۔
جس بات پر ہمارا پختہ یقین اور اعتقاد ہے اورجس کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ اللہ کی بندگی ہے جس کی طرف برگزیدہ انبیا ورُسل، ابوالبشر سیّدنا آدمؑ سے لے کر خاتم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نے بلایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اقرار اور عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ ہی اپنے بندوں کا حقیقی حاکم اور لائقِ اتباع واطاعت ذات ہے۔ وہی قانون و دستور کا شارع اور امور و معاملات کا مالک ہے۔ وہی ان کے امور و معاملات کا متصرف اور وہی ان کے اعمال و افعال کامحاسب ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ بندہ اسی مقتدر و قادرِ مطلق اللہ کے حوالے اپنی پوری زندگی کر دے اور اپنے دین کو اسی بلند وبرتر کے لیے خالص کرلے۔ اپنی انفرادی واجتماعی زندگی کے اخلاقی و سیاسی، معاشی و سماجی تمام امور میں اسی کی عبادت و عبودیت کا عقیدہ دل و دماغ میں بٹھا لے۔ اسی مفہوم میں قرآن عظیم کی یہ آیت نازل ہوئی:
يٰٓاَيُّہَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَاۗفَّۃً ۰۠ (البقرۃ۲:۲۰۸) اے ایمان لانے والو! تم پورے کے پورے اسلام میں آجائو۔
وہی اللہ اس آیت میں اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اس کے دین میں داخل ہو جائیں۔ اپنی پوری زندگی کو اس کے دین کے تابع کر دیں۔ تاکہ کوئی شے اس کی حکمرانی سے باہر اور زندگی کے شعبوں میں سے کوئی شعبہ اس کی حکمرانی کے دائرۂ نفوذ و نفاد سے باہر نہ رہے۔ تمھارے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی کے گوشوں میں سے کسی گوشے اور شعبے میں اُس کی کامل بندگی سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھو، یا اپنے معاملات میں جن خود ساختہ طریقوں اور نظاموں کو چاہو اختیار کر لو، اور جن دساتیر و قوانین کی چاہو پیروی کرو۔ بندگی کا یہ مفہوم ہم تمام مسلمانوں اور غیرمسلموں میں پھیلانا اور عام کرنا چاہتے ہیں اور اسی کی ہم دعوت دیتے اور تبلیغ کرتے ہیں، کہ تمام انسانیت اسی کو قبول کرے، اسی پر ایمان و یقین رکھے۔
دوسری چیز جس کا ہم ایمان کے دعوے داروں سے مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نفاق کی تمام شکلوں اور اپنے اعمال کو تناقض کے تمام مظاہر سے پاک کرلیں۔
نفاق یا منافقت سے ہماری مراد یہ ہے کہ انسان ایک خاص نظام پر ایمان کا دعویٰ کرے، اور اس کی طرف نسبت و انتساب کا سچا جھوٹا مظاہرہ بھی کرے۔ پھر اسی نظام کے بالکل برخلاف نظامِ حیات میں راضی و مطمئن زندگی گزارتا رہے۔ اپنے ایمان کے منافی نظام کے خلاف اس کے دل میں کوئی اضطراب پیدا نہ ہو۔ وہ اپنے دین کے نفاذ کے لیے کبھی جدوجہد نہ کرے، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنی صلاحیتوں اور طاقتوں کو، اپنی مساعی اور کاوشوں کو اسی فاسد و فاسق اور ظالم نظام کی جڑیں مضبوط کرنے، یا ایک باطل نظام کی جگہ دوسرے باطل نظام کو قائم کرنے میں اپنی طاقتیں صرف کر دے، یا پھر اسی ظالمانہ نظام کے فروغ و ارتقا میں اپنی زندگی کھپا دے اور اپنے آپ کو پُرسکون و مطمئن اور مومن و مسلمان بھی سمجھتا رہے۔ ایسے لوگوں کو منافق ہی سے تشبیہ دی جاسکتی ہے کیونکہ ایمان کسی ایک نظام پر رکھنا اور مطمئن کسی دوسرے نظام پر ہوجانا،آپس میں بالکل متضاد باتیں ہیں۔ یہ ایسی بات اور صورت حال ہے جس کو سن کر کان اس کی تصدیق کے لیے تیار نہ ہوں، عقل اس کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، اور شریعت کی میزان پراس کو تولا جائے تو وہاں اس کا کوئی وزن نہ ہو۔
یہ بات ایمان کے بالکل بنیادی مقتضیات میں سے ہے کہ آدمی کو دل کی گہرائیوں سے یہ بات پسند ہو کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند و بالا اور ارفع واعلیٰ ہو۔ اور یہ کہ دین تمام کا تمام الله ہی کے لیے ہوجائے۔ اور یہ کہ اس روئے زمین پر اسلام کا پرچم اٹھانے والوں اورانسانیت کے لیے یہ ذمہ داری ادا کرنے والوں کا کوئی مخالف و مزاحم نہ ہو۔ وہ اس دین پر آنے والی آنچ دیکھے یا اس کے دائرۂ اثر کی حکمرانی، تو اس کی روح بے قرار ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی ایمان کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ جب تک اس دین کے نظامِ عدل کو غالب اور برسرِکار نہ دیکھ لے، بے چین ومضطرب اور بے سکون وناخوش رہے۔ دین کی حکمرانی، اس کے پرچم کی سربلندی اور اس کے کلمے کا نفاذ ہی اس کے لیے باعث ِراحت و سکون ہو۔
ایمان کی ان علامات اور نشانیوں پر بحث سوائے کسی ہٹ دھرم اور جھگڑالو کے کوئی نہیں کرسکتا۔ اور یہ بات بھی ناقابلِ بحث ہے کہ آدمی ان عصری باطل نظاموں پرراضی و مطمئن ہو کر زندگی گزارتا رہے، جن میں دین کا کہیں کوئی غلبہ نہ ہو۔ بلکہ ان نظاموں نے دین کو نکاح و طلاق اور وراثت کے نہایت محدود اور تنگ دائرے تک محدود کر دیا ہو، جس سے ان جاری ظالمانہ نظاموں کو کوئی خطرہ نہیں اور نہ یہ مسائل ان کے حدودِ سلطنت و امارت میں کوئی دخل دیں ___ یا آدمی اس طرح کے نظاموں میں مطمئن زندگی گزارتا رہے، وہ انھی پر صابر ومطمئن ہو جائے اور نہ اس کی رگِ حمیت پھڑکے۔ بخدا، اس طرح کا رویہ بلا شک وشبہ نفاق کی نشانیوں میں سے ہے۔
اس قسم کے آدمی کو فقہاءو مشائخ کی طرف سے رعایت مل سکتی ہے اور وہ فتاویٰ کے مجموعوں اور شماریات کے رجسٹروں میں تو مسلمان رہ سکتا ہے، مگر شریعت کی روح اس طرح کے رویے کو نفاق کے علاوہ کچھ اور قرار نہیں دیتی، خواہ ان مفتیان کے فتوے اس کے خلاف ہی ہوں، جن کا مقصد محض اس فانی دنیا کا حصول ہے۔
لہٰذا، وہ چیز جس کی ہم مسلمانوں اور اسلام کا مظاہرہ کرنے والوں کو دعوت دیتے ہیں، یہ ہے کہ وہ دین کو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خالص کرلیں اور اپنے آپ کو نفاق کی تمام آلائشوں سے پاک کر لیں۔ اس ایمان کا یہ حق بھی ہے کہ آدمی اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں میں یہ تمنا اور آرزو رکھے کہ زندگی اور حکومت کا نظام، معیشت و معاشرت کے طور طریقے وہی ہوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور وہی دنیا میں نافذ و سربلند ہوں۔
کوئی ہٹ دھرم ان کا راستہ نہ روک سکے اور کوئی رکاوٹ ان کی راہ میں حائل نہ ہونے پائے، کجا کہ وہ اس کے برعکس نظام پر راضی رہے اور اسی کے تحت زندگی گزارنے پر مطمئن ہوجائے۔
باقی رہا وہ شخص جو باطل نظاموں کی جڑیں مضبوط کرنے کی سعی کرے اور اسی کو سر بلند کرنے میں کوشاں ہو، ایسا شخص بلاشبہ گمراہی، بے راہ روی اور ہٹ دھرمی کا شکار ہے۔
نفاق کے ساتھ دوسری چیز تناقض ہے، جس کو اپنی زندگیوں سے خارج کرنے کی ہم نئے اور پرانے تمام مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تناقض کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کا عمل اس دعوے کے خلاف ہو، جو وہ اپنی زبان سے کرتا اور اپنے اقوال میں ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی تناقض ہے کہ آدمی کا عمل زندگی کے مختلف مسائل میں یکساں نہ ہو۔ کسی پر بہت زور ہو اور کوئی بالکل نظر انداز ہو کر رہ جائے۔اسی طرح یہ بھی اسلام پہ ایمان نہیں ہے کہ آدمی زندگی کے شعبوں میں سے کسی ایک شعبے میں تو احکام الٰہی کو مان کر دے، مگر دوسری طرف حدودِ شریعت سے تجاوز کو وتیرہ بنائے رکھے۔ نہیں، یہ نہیں بلکہ ایمان کے تقاضوں میں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور اپنی پوری زندگی کو دینِ حق کی نگرانی میں دے دے۔ وہ احکامِ الٰہی میں سے کسی حکم کی بھی نافرمانی نہ کرے۔ وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے ایسے فعل کا بھی ارتکاب نہ کرے، جس سے اللہ کی کامل بندگی اور دین و شریعت کی کامل پیروی میں ذرا سا بھی نقص واقع ہوتا ہو۔ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، دنیا کی فتنہ انگیز کوئی شے اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ وہ اپنے اعمال و افعال میں صراطِ مستقیم سے ذرا منحرف نہ ہو۔ یہ بھی علاماتِ ایمان میں سے ہے کہ جب بھی کوئی برائی اور نافرمانی سرزد ہو جائے، تو مومن اپنے اللہ سے معافی مانگے اور اس کی طرف رجوع کرے۔
لیکن آدمی اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرے، نماز، روزہ ه اور بعض متعین شعائر کی ادائیگی بھی کرے اور پھر خود کو آزاد و خود مختار سمجھ لے، کسی قیدو قدغن کی پروا کرے اور نہ کسی حکم الٰہی کو عملی زندگی میں مانے، یہی وہ تناقض ہے جو بندگی کے منافی ہے۔
آپ اس شعبدہ بازی کے بارے میں کیا کہیں گے، جو آج کے مسلمان پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں اور ایمان بالله اور ایمان بالآخرہ کابلند بانگ دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اسلام کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور اس کی بعض علامات کو بھی اپنا رکھا ہے۔ لیکن جونہی عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، سیاست کے میدان میں قدم رکھتے ہیں اور معیشت و معاشرت کے مسائل میں بحث کرتے ہیں، تواسلام کی تعلیمات ان کو چھو کر بھی نہیں گزرتیں۔ دین حق اور شریعت کاملہ کے پیروکاروں کے اثرات ذرا بھی ان کے اوپر دکھائی نہیں دیتے۔ یہ دو رنگی اور شعبدہ بازی نہیں تو اور کیا ہے؟
وہ دن رات یہ اقرار کرتے نہیں تھکتے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور اس کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ لیکن ساتھ ہی وہ ہر نااہل کے پیچھے چلنے میں ذر ابھی حرج محسوس نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ انھیں اللہ کی زمین پر کسی جابر و متکبر کے سامنے جھکنے اور اس کے حکم کی بجاآوری میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی۔
یہ ہے وہ تناقض و تضاد اور اس کی علامات، جو مسلمانوں کی تمام اخلاقی و معاشرتی بیماریوں کا سبب ہیں۔ اور جب تک ان کے اندر یہ مہلک اخلاقی امراض باقی رہیں گے، ان کے زوال وذلت اور انحطاط و پسماندگی کے مرض سے شفایابی کی اُمید نہیں۔ نہ اس پستی سے ان کے نکلنے کی اُمید ہے جس میں یہ گر چکے ہیں۔
لیکن یہاں جس بات پر دل خون کے آنسوروتا ہے وہ مسلمان علما و مشائخ کا رویہ ہے جنھوں نےان کو یہ یقین دلارکھا اور اس پر مطمئن کر رکھا ہے کہ دین کے معاملات میں بس وہ کلمۂ شہادت کا اقرار کرلیں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، یہ چند متعین و محدود رسومِ عبادت ادا کر لیں تو اُن کے لیے کافی ہے۔
اگر وہ اتنا کرلیں تو نجات اور جنّت کے دروازے ان کے لیے بند نہیں ہو سکتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جتنی برائیاں چاہیں کرلیں، کفرو ضلالت کے جن اماموں کی چاہیں پیروی کر لیں، وہ جو چاہیں اپنی خواہشِ نفس کے تحت غلط اور باطل نظریات وافکار کو اختیار کر سکتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ان کی بے باکی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ دینِ اسلام کا اقرار ہی کافی سمجھتے ہیں اور فرائضِ شریعت کی ادائیگی کی ضرورت تک محسوس نہیں کرتے۔
ائمہ کفر و ضلال تو ایک قدم اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں جیسے نام رکھ کر اور ان کے رجسٹروں میں اندراج کر اکے مسلم وغیرمسلم حکومتوں کے مناصب پر متمکن ہوجاتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ایسے ہی لوگوں کی تصویر دکھائی گئی ہے:
وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّـنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَۃً ۰ۭ (البقرۃ ۲:۸۰) وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، اِلّایہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔
مسلمانوں کے بدنوں اور روحوں کو لگی اس پیچیدہ اور دیرینہ بیماری کے ہی یہ نتائج ہیں کہ وہ کمیونزم، نازی ازم، کپیٹل ازم اور مادر پدر آزاد جمہوریت وغیرہ جیسے مغرب سے درآمدہ جدید نظاموں کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ انھی ظالم اورجابر لوگوں کے نقشِ قدم پر چل رہے ہیں جو اللہ کی زمین پر ناحق تکبر کے مظاہرے کرتے پھرتے ہیں۔ ان میں مسلمان حکمران بھی شامل ہیں اور غیرمسلم حکمران بھی ___ ان لوگوں کو اس میں کسی حرج اور نقصان کا ذرا اندیشہ نہیں محسوس ہوتا۔ انھیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ خدا کے ان باغیوں اور سرکشوں کے طریقے اسلام کے نظامِ زندگی کے بالکل برعکس ہیں۔
ہماری دعوت کے بنیادی نکات میں یہ بات شامل ہے کہ ہم ہر مسلمان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے قائم ہر تعلق کو توڑ کر اپنے تعلق کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لے اور یکسو اور یک رُخ ہو کر اسی کا بندہ بنے۔ وہ ہر قسم کی عصبیت سے نکل جائے۔ نظریۂ حق کے مخالف اور معارض ہر فکر و نظر سے اپنا رخ پھیر لے اور پھر اس پر قائم رہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو تدریجاً ان ٹیڑھے اور غلط راستوں سے کٹ جانے کی مسلسل جدوجہد کرتا رہے۔(جاری)
’احسان‘ حُسن سے بنا ہے جس کے معنی اچھائی کے ہیں: ۱- یہ اچھائی ظاہری بھی ہوسکتی ہے، یعنی خوب صورتی۔۲-یہ اچھائی معنوی یا روح کے لحاظ سے ہوسکتی ہے، مثلاً کوئی اچھا کام یا نیکی۔ ۳- یہ عمومی اچھائی بھی ہوسکتی ہے جوعقل کے معیار پر پوری اترتی ہو یا دل کو بھلی لگتی ہو۔ ایک تعریف کے لحاظ سے حواسِ ظاہر ی(بصارت، سماعت، شامہ، ذائقہ) یا حواسِ باطنی (بصیرت یا عقل) اس کے اچھے ہونے کا فیصلہ دیں۔
اس طرح خوب صورت انسان، خوب صورت مناظر، علمی نکات و لطائف، خوش ذائقہ چیزیں، دلآویز خوشبوئیں،ان سب میں حُسن پایا جاتا ہے۔
حسن سےبنائے گئے کچھ الفاظ یہ ہیں: • جس چیز میں حُسن یا اچھائی پائی جائے ، وہ حسَن (مذکر) ہے ، یا حسَنَۃ اور حسنات (مؤنث) ہیں۔انسان کے لیے حسنۃ ہر وہ نعمت ہے جس کا اثر انسان اپنے نفس، بدن اور احوال میں محسوس کرسکے۔ حسنۃ کی ضد سیئۃ ہے۔
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۔۔۔(الرعد۱۳:۶) یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچارہے ہیں۔
• جس میں سب سے زیادہ اچھائی پائی جائے ،وہ احسن(مذکر ) اور حسنیٰ (مونث) ہیں۔
کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کو احسان (باب اِفعال) کہتے ہیں۔ یہ اچھائی کرنے والے محسن اور محسنون (مذکر)، محسِنۃ اور محسِنات (مؤنث) ہیں۔اور احسان کی ضد اِساءۃ ہے۔
احسان کے مفہوم میں عمومی اچھا عمل یا نیکی بھی شامل ہے، لیکن اس سے خصوصی مراد بہت حسن کے ساتھ کیا گیا عمل ہوتا ہے۔
سیّد مودودی کے بقول: ’’احسان دراصل اللہ اور اس کے رسولؐ اور اس کے دین کے ساتھ قلبی لگائو، اس کی گہری محبت، اُس سچی وفاداری اور فدویت و جانثاری کا نام ہے جو مسلمانوں کو فنا فی الاسلام کردے۔ تقویٰ کا اساسی تصور خدا کا خوف ہے جو انسان کو اس کی ناراضی سے بچنے پر آمادہ کرے، اور احسان کا اساسی تصور خدا کی محبت ہے جو آدمی کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اُبھارے‘‘۔ (تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں)
خالق کے احسان،نعمتوں کی شکل میں بے انتہا ہیں جن کو ہم شمار بھی نہیں سکتے:
وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَۃَ اللہِ لَا تُحْصُوْہَا۰ۭ (النحل۱۶:۱۸) اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔
وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْہُ۰ۭ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللہِ لَا تُحْصُوْہَا(ابراہیم ۱۴:۳۴) جس نے وہ سب کچھ تمھیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔
ان احسانات کے لیے قرآن میں نعم، منّ اور اٰلاء کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس زمین کی ساری موجودات کے لیے،جن میں ہم بھی شامل ہیں، خالق کا سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا،اور ان سب موجودات کے بیچ جانداروں کے گروہ سے ہمارا تعلق بنایا۔ ہر جاندار کی طرح ہمیں زندگی یا روح عطا کی۔ جسمانی حصے اور ایک ایک عضو بنایا اور متناسب بنایا۔ ایٹمز اور مالیکیولز کو ملا کر خلیات، اور انھیں ملا کر جسم کے مختلف نظام بنائے جو ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں اور مربوط بھی۔انسانی ساخت (Anatomy) کے علاوہ جسمانی افعال (Physiology)کی بھی حیران کن، مربوط اور متنوع چیزیں دیں۔حواس ِ خمسہ، چال، آواز کا نظام voluntary حرکات involuntary حرکات جو جسم میں متعدد جگہوں پر جاری رہتی ہیں۔نیند کی شکل میں آرام اور نئے سرے سے تازگی کا، برسوں چلنے والا نظام دیا۔ پھر جسم کو ایک نعمت جوانی کی شکل میں دی، اور اس کے ساتھ حسن دیا اور صحت دی۔
اس ربّ نے دنیا کی سب چیزوں کی پرورش کے لیے نظام بنایا ہے۔آسمان اور اس کے ساتھ سورج جسے حرارت اور روشنی کا منبع بنایا ہے۔ چاند، ستارے اور اجرامِ فلکی کی لامتناہی دنیا بنائی ہے۔ زمین اور اس پر موجود چیزوں کے ساتھ ان کا تعلق قائم کیا، جو مناسب فاصلوں، گردشوں اور اپنے دائروں میں تیرنے کے باعث دن رات بناتا ہے، موسموں کو بدلتا ہے، ہوا اور اس کی گیسوں، پانی اور بادل اور بارش اور آبی ذخائر کو منظم کرتا ہے۔ زمین پر پہاڑ ، آگ اور عناصر کے ذخیروں اور گردش کو منضبط کیا۔اس نے جانوروں اور نباتات کی ایک ایک جنس اور ان کے آپس کے ایکوسسٹم کی تنظیم کررکھی ہے۔یہ اس دنیا کی ہر جان دار و بے جان چیز کی پرورش کا بھی انتظام ہے اور ساتھ ہی ایک کامل نظام کا وجود بھی جس میں کوئی تفاوت یا فتور نہیں۔اس نے اس کائنات کو حُسن دیا، آہنگ ورنگ و بو دیئے، انسانوں کی شکل اور زبانوں کاتنوع دیا۔ہر چیز زوج، جوڑے کی صورت میں پیدا کی جو اپنا مقصدپورا کررہی ہے۔
اس نے انسان کی پرورش کے بے شمار انتظامات کیے:جسمانی نشو و نما کے لیے غذا دی جس میں محض غذائیت نہیں، افراط، لذت اور تنوع بھی ہے۔غلے کے ایک ایک دانے کی تشکیل کےلیے کائنات کے متعدد عوامل کو لگایا۔لباس اور گھر کا تنوع کے ساتھ انتظام کیا۔ جسمانی آرائش کے ، سفر کے، لذت کے اور کاموں میں سہولت کے سامان دیئے۔
علم الامراض (Pathology) حاصل کرتے ہوئے ہزاروں امراض کا علم ہوتا ہے جو کہ ہوسکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بچایا ہوا ہے ، یہ بھی اس کا احسان ہے۔اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس نے بیماری کے ساتھ ان کی علامتیں رکھ دیں، مثلاً بخار، درد یا حسی نظام کے ذریعے، کہ ان کو پرکھ کر بیماری کی تشخیص کرلی جائے۔ اس نے بیماریوں کے علاج بھی اسی دنیا میں رکھ دیئے ہیں۔اور وہی ہے جو جسمانی تکلیف کو دُور کرتا ہے اور بیماریوں سے شفاء دیتا ہے۔وہ آفات سے بچاتا اور حفاظت کرتا ہے اور انھیں دور بھی کرتا ہے۔ عافیت اور سلامتی اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ جس نے موت بھی تخلیق کی ہے ۔ موت نہ ہو اور کئی سو سالہ زندگی ،موجودہ انسانی جسم کے ساتھ ہو تو اس کا کرب ایک، سو سالہ موجودہ انسان محسوس کرسکتا ہے۔یہ موت ایسے بھی ایک نعمت ہے کہ صبحِ دوامِ زندگی ہے۔
انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص احسان یہ ہے کہ اسےاحسنِ تقویم پر پیدا کیا اور اپنی روح پھونکی ،اسےتعدیل اورتسویہ (توازن، مناسبت) کے ساتھ خلق کیا۔ اسے اشرف المخلوقات بنایا اور تکریم دی (بنی اسرائیل ۱۷:۷۰)۔اسے غیر معمولی عقل اور ذہنی صلاحیتیں دیں جن میں مشاہدہ، حافظہ، حساب،پیش بینی، استدلال، تجزیہ، استنباط شامل ہیں۔ اس کے لیے لامتناہی علم کا دروازہ کھولا، جو اسے معرفت اور حکمت تک لے جاتا ہے۔اور اس علم اور عقل کے استعمال کے ساتھ اسے بیان سکھایا(الرحمٰن۵۵:۴) جس میں مختلف زبانیں، قوت ناطقہ، فصاحت و بلاغت، لہجے اور اسالیب ِبیان شامل ہیں۔تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کو آسان کیا اور انھیں سنبھلنے کی مہلت دی۔
انسان کو ایک نعمت ذہنی سکون کی شکل میں بھی ملتی ہے۔انسان کا مالک اسےغم اور خوف سے نجات دیتا ہے۔ ذہنی آسودگی کے اسباب میں اسے محبتیں، رشتے اورتعلقات دیئے ہیں۔دلوں میں رحم کے ذریعے آپس میں رحم کو پھیلایا ہے۔انسان کوجو عزّت ملتی ہے، آزادی کی ہوا میں سانس لیتا ہے ، دنیا میں پھیلی ہوئی خوب صورتی سے محظوظ ہوتا ہے، چھوٹی بڑی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، دیگر خوشیاں ملتی ہیں،کبھی سکینت کی کیفیت ہوتی ہے___سب اس الوھاب کے احسانات ہیں۔ وہ امتحان کے تقاضوں کے تحت غم اور مشکل بھی دیتا ہے، لیکن اس نے غموں کے بعد راحت، اور مشکل (عسر) کے ساتھ آسانی(یسر) رکھ دیئے ہیں۔
انسان کو بحیثیت فرد کے علاوہ بحیثیت نوعِ انسانی اجتماعی نعمتیں بھی دی ہیں، مثلاً تسخیرِ وسائل، تمدنی ترقی و ایجادات، سفر کے ذرائع، کام کے لیے اوزار و آلات و مشینیں، انسانی وسائل کا تخصص کے ساتھ استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عاد اور ثمود کو ایسی ہی اٰلاء یاد دلائی ہیں۔ بستیوں کی خوش حالی اور امن، وہ بھی نعمتیں ہیں۔جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے برکت، فضل اور غناء ملی ہیں ، وہ بھی بیش بہا نعمتیں ہیں۔ ان عطا کردہ نعمتوں میں براہِ راست نعمتیں بھی ہیں اور ان کے پیچھے بالواسطہ نعمتیں بھی بے شمار ہیں۔ ان میں وہ نعمتیں بھی ہیں، جو ہمیں معلوم ہیں اور وہ نعمتیں بھی جن کا ہمیں علم نہیں۔
•انسانوں کے زمرے میں مومنین پر اس کا خاص احسان یہ ہے کہ انھیں ہدایت دے کر جنت کا راستہ آسان کردیا ہے۔مومنوں کو نفس مطمئنہ کی دولت دی ہے۔ ان کے لیے دعاؤں کا دروازہ کھولا ہے، ان کے استغفار و توبہ کو قبول کیا جاتا ہے، ان کی نیکیوں کو قدر وقبولیت بخش کر ان میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ آخرت میں ان کے لیے جنت سجائی گئی ہے جوان کے اعمال نہیں بلکہ رحمٰن کی رحمت کا کمال ہے۔وہاں کی نعمتوں کا تصور نہیں کیا جاسکتا اور وہاں انسان اس جسم کے ساتھ ہوگا جو ابدی جوانی کے ساتھ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔
اُمتِ مسلمہ کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو رحمۃ للعالمینؐ ہیں، اور اس کو اپنا احسان کہا: لَقَدْ مَنَّ اللہُ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ (ال عمرٰن ۳: ۱۶۴)۔ ان کے ساتھ ایک مکمل کتاب دی جو محفوظ کردی گئی ہے،اس امت کوکم وقت میں زیادہ کام کے اجر کی بشارت دی گئی ہے،اور اس کو پچھلی قوموں کی طرح کے عذاب سے بچایا گیا ہے۔
ان میں سے بھی جن لوگوں کو ایمان اور عمل کا زیادہ شعور ملا، اچھی صحبت اور ماحول مل گیا، کوئی صالح اجتماعیت مل گئی ،تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص احسانات ہیں۔
آزادی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر، حفاظت اور تشکر کا احساس ہروقت ذہنوں پر غالب رہنا چاہیے۔کسی خطے میں یا کسی کے خاندان اور گھرانے پر، اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص احسان ہو تو اس کی قدر بھی ہونا چاہیے۔کسی جگہ یا کسی بھی دائرے میں تھوڑا سا بھی اقتدار ایک نعمت ہے۔
حضرت یوسفؑ نے اپنے اوپر اللہ کےاحسانات کا ذکر کیا:
اِنَّہٗ رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ۰ۭ (یوسف۱۲:۲۳) میرے ربّ نے تو مجھے( احسن) منزلت بخشی۔
وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ (یوسف۱۲:۱۰۰) اس کا احسان ہے کہ اُس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔
قرآن میں مذکورحضرت ابراہیم ؑ اور حضرت سلیمانؑکی دعائیں بھی اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اقرار ہیں(ابراہیم۱۴: ۳۹، النمل۲۷: ۱۵)
• طب کا علم رکھنے والوں کو اس علم کی، اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پہ بھی قدر کرناچاہیے:
فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ۱۶ (الرحمٰن۵۵:۱۶) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
لَا بِشَیءٍ مِّنْ نِّعَمِکَ رَبَّنَا نُکَذِّبُ، اے ہمارے رب! ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔
اور یہ سب نعمتیں امانتیں بھی ہیں اور ذمہ داریاں اور امتحان کے پرچے بھی۔
انکارِ نعمت یا کفرانِ نعمت: نعمت کو نعمت نہ سمجھنا، مثلاً ہدایت ِ الٰہی یا قرآن کو بے فائدہ سمجھنا یا تحقیرکرنا یا بے نیازی کا رویہ رکھنا۔ یہ انکارِ نعمت یا کفرانِ نعمت ہے۔
نعمت کااحساس نہ ہونا: نعمت کو کسی منعم کی عطا نہ سمجھنا یا کسی کو خالق نہ سمجھنا اور سب چیزوں کو اتفاقی حادثہ سمجھنا۔
منعم کے ساتھ دوسروں کوشریک کرنا:یہ سمجھنا کہ جو کچھ ملا ہے وہ ہماری اپنی محنت سے یا عقل سے ملا ہے،یا یہ زعم رکھنا کہ ہم اس کے مستحق تھے اور ہمیں تو یہ سب ملنا ہی چاہیے تھا۔ وجود سے لے کرہرچھوٹی بڑی چیز کو منعم کی عطا مان لینا لیکن اطاعت کا حق تسلیم نہ کرنا، •یا اطاعت کا حق ماننا، لیکن عملاً اطاعت نہ کرنا اور نافرمانی اور سرکشی کی روش رکھنا۔
اعترافِ احسان اور شکر یہ ہے کہ:جس کی نعمتوں کا شمار نہیں، اس منعِم کا حق ہے کہ اس کو ہروقت یا د رکھیں اور کسی ساعت اس سے غفلت نہ ہو۔ان نعمتوں کا احساس رکھیں اورحمد، یعنی صرف اللہ کی تعریف اور شکر کرتے رہیں۔
•نعمتوں کے تقاضے اور ذمہ داریاں پورا کرتے رہیں، وہ قلبی ہوں، قولی ہوں یا عملی۔ یہ تقاضے نعمتوں کی اقسام کے لحاظ سے ہوسکتے ہیں، مثلاً: نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ جسمانی قویٰ، صلاحیتوں، وقت، مادی چیزوں، ذہن و فکر کو اللہ کے راستے میں ہی استعمال کریں۔ اُن کا ضیاع نہ کریں، مثلاً پانی کے ذخیروں کے پاس بھی احتیاط کریں۔ کھانا، بجلی،گیس کے استعمال میں ضیاع سے بچیں۔
اجتماعی نعمتوں کی حفاظت کریں، مثلاًپانی، ہوا، زمین، درختوں کی حفاظت کریں۔ آلودگی سے بچنے والے اقدامات کریں۔قابلِ اشتراک نعمتیں دوسروں کو دیں، مثلاً مال،کھانا، کپڑے، علم۔
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کو ناراض کرنے سے بچیں جیسا کہ حضرت یوسفؑ اللہ کے احسان کو یادکرتے تھے اور نافرمانی سے بچتے تھے۔(یوسف۱۲:۲۳)۔شکر کا رویہ پوری زندگی میں منعمِ حقیقی کے آگے سرتسلیم خم کرنے سے ظاہر کریں۔اس میں اپنا فائدہ بھی ہے (لقمان۳۱:۱۲، النمل۲۷:۴۰)، پرسشِ قیامت کی آسانی بھی ہے (التکاثر۱۰۲:۸)، اور یہی رویہ عذاب سے بچاتا ہےاور نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ (ابراہیم۱۴: ۷)
حدیث ِ جبریلؑ میں ہے: قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْاِحْسَانُ قَالَ الْاِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (بخاری) ’’اس شخص نے پوچھا: یارسول ؐ اللہ!احسان کیا ہے؟۔ آپ ؐ نے فرمایا: احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، تو وہ تمھیں دیکھ رہا ہے‘‘۔
اس حدیث کے مطابق احسان یہ ہے کہ اللہ جل شانہٗ کی ذات اوروجود کا احساس اور تصور رکھا جائے۔یہ احساس اللہ تعالیٰ کے لیے دیگر قلبی کیفیات کی بنیاد ہے جیسے اللہ سے محبت، خشیت، تعظیم، تکبیر، امید، اخلاص وغیرہ۔ ہر عمل عبادت کے ساتھ احسان کی یہ کیفیت ہو تو اس عبادت کو خوب صورتی عطا کرتی ہے۔جس طرح ایک وڈیو کیمرے کی موجودگی انسان کو محتاط کردیتی ہے ، اسی پر اس احساس کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ زندگی کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے احساس کے ساتھ ادا کیے جائیں تو وہ احسان بن جاتے ہیں۔تصوف میں ’احسان‘ کی اصطلاح کا یہی مطلب ہے۔
احسان کا ایک مفہوم جو پہلے مفہوم کی تفصیل ہی ہے، وہ یہ ہےکہ احسان اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ہے کہ جو فرماںبرداری کی انتہا تک لےجائے۔
سید مودودی اسلامی اخلاقیات کے چار مراتب کے ضمن میں رقم طراز ہیں: ’’ایمان، اسلام، تقویٰ اور احسان___ یہ چاروں مراتب یکے بعد دیگرے اس فطری ترتیب پر واقع ہیں کہ ہر بعد کا مرتبہ پہلے مرتبے سے پیدا اور لازماً اسی پر قائم ہوتا ہے۔احسان دراصل اللہ اور اس کے رسولؐ اور اس کے دین کے ساتھ اس قلبی لگاؤ، اس گہری محبت، اس سچی وفاداری اور فدویت و جاں نثاری کا نام ہے جو مسلمان کو فنا فی الاسلام کردے۔ تقویٰ کا اساسی تصور خدا کا خوف ہے جو انسان کو اس کی ناراضی سے بچنے پر آمادہ کرے، اور احسان کا اساسی تصور خدا کی محبت ہے جو آدمی کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے پر اُبھارے‘‘۔(تحریکِ اسلامی کی اخلاقی بنیادیں )
اگر احسان فرماں برداری کی انتہا ہے تو یہ ہر نیک کام میں ہونا چاہیے۔ لیکن احسان کےایک مفہوم کے مطابق ان سب کاموں میں سے چوٹی کا کام اللہ کا کلمہ بلند کرنے کا کام ہے اور اس کو خصوصاً احسان کہا گیا ہے۔مندرجہ ذیل اقتباسات اس کی وضاحت کرتے ہیں:
’’ان دونوں چیزوں کے فرق کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ حکومت کے ملازموں میں سے ایک تو وہ لوگ ہیں جو نہایت فرض شناسی و تن دہی سے وہ تمام خدمات ٹھیک ٹھیک بجا لاتے ہیں جو ان کے سپرد کی گئی ہوں۔ تمام ضابطوں اور قاعدوں کی پوری پوری پابندی کرتے ہیں اور کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو حکومت کے لیے قابلِ اعتراض ہو۔ دوسرا طبقہ ان مخلص وفاداروں اور جان نثاروں کا ہوتا ہے جو دل و جان سے حکومت کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ صرف وہی خدمات انجام نہیں دیتے جو ان کے سپرد کی گئی ہوں، بلکہ ان کے دل کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ سلطنت کے مفاد کو زیادہ سے زیادہ کس طرح ترقی دی جائے۔اس دھن میں وہ فرض اور مطالبہ سے زائد کام کرتے ہیں۔ سلطنت پر کوئی آنچ آئے تو وہ جان و مال اور اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوجاتے ہیں۔ قانون کی کہیں خلاف ورزی ہو تو ان کے دل کو چوٹ لگتی ہے۔ کہیں بغاوت کے آثار پائے جائیں تو وہ بے چین ہوجاتے ہیں اور اسے فرو کرنے میں جان لڑا دیتے ہیں۔ جان بوجھ کر خود سلطنت کو نقصان پہنچانا تو درکنار اس کے مفاد کو کسی طرح نقصان پہنچتے دیکھنا بھی ان کے لیے ناقابلِ برداشت ہوتا ہے اور اس خرابی کے رفع کرنے میں وہ اپنی حد تک کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بس ان کی سلطنت ہی کا بول بالا ہو اور زمین کا کوئی چپہ ایسا باقی نہ رہے جہاں اس کا پھریرا نہ اُڑے۔
’’اسلام کی اصل طاقت محسنین کا گروہ ہے۔ اصلی کام جو اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں ہو، وہ اسی گروہ سے بن آسکتا ہے۔جو لوگ اپنی آنکھوں سے خدا کے دین کو کفر سے مغلوب دیکھیں ، جن کے سامنے حدود اللہ پامال ہی نہیں بلکہ کالعدم کردی جائیں، خدا کا قانون عملاً ہی نہیں بلکہ باضابطہ منسوخ کردیا جائے ، خدا کی زمین پر خدا کا نہیں بلکہ اس کے باغیوں کا بول بالا ہو رہا ہو، نظامِ کفر کے تسلط سے نہ صرف انسانی سوسائٹی میں اخلاقی وتمدنی فساد برپا ہو بلکہ خود اُمتِ مسلمہ بھی نہایت سرعت کے ساتھ اخلاقی و عملی گمراہیوں میں مبتلا ہورہی ہو، اور یہ سب دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں نہ کوئی بے چینی پیدا ہو، نہ اس حالت کوبدلنے کے لیے کوئی جذبہ بھڑکے ، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنے نفس کو اور عام مسلمانوں کو غیر اسلامی نظام کے غلبے پر اصولاً و عملاً مطمئن کردیں، ان کا شمار آخر محسنین میں کس طرح ہوسکتا ہے؟
’’آپ دنیوی ریاستوں اور قوموں میں بھی وفادار اور غیر وفادار کی اتنی تمیز ضرور پائیں گے کہ اگر ملک میں بغاوت ہوجائے یا ملک کے کسی حصے پر دشمن کا قبضہ ہوجائے تو باغیوں اور دشمنوں کے تسلط کو جو لوگ جائز تسلیم کرلیں یا ان کے تسلط پر راضی ہوجائیں اور ان کے ساتھ مغلوبانہ مصالحت کرلیں ، یا ان کی سرپرستی میں کوئی ایسا نظام بنائیں جس میں اصلی اقتدار کی باگیں انہی کے ہاتھ میں رہیں اور کچھ ضمنی حقوق اور اختیارات انھیں بھی مل جائیں، تو ایسے لوگوں کو کوئی ریاست اور کوئی قوم اپنا وفادار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ، خواہ وہ قومی عادات و اَطوار کے کیسے ہی سخت پابند اور جزئی معاملات میں قومی قانون کے کتنے ہی شدید پیرو ہوں۔
’’ان سب ریاستوں اور قوموں کے پاس وفاداری کو جانچنے کا ایک ہی معیار ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے دشمن کے تسلط کی مزاحمت کس حد تک کی، اس کو مٹانے کے لیے کیا کام کیا اور اس اقتدار کو واپس لانے کی کیا کوشش کی جس کی وفاداری کا وہ مدعی تھا۔ پھر کیا معاذ اللہ خدا کے متعلق آپ کا یہ گمان ہے کہ وہ اپنے وفاداروں کو پہچاننے کی اتنی تمیز بھی نہیں رکھتا جتنی دنیا کے ان کم عقل انسانوں میں پائی جاتی ہے؟‘‘…(تحریکِ اسلامی کی اخلاقی بنیادیں)
احسان کے اس مفہوم کو ہم ایسے بیان کرسکتے ہیں :اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ساری قابلیت اور سارے وسائل صرف کردینا، دل و جان سے اس کی تکمیل کی کوشش کرنا۔یہ مفہوم درج ذیل آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے:
وَالَّذِيْنَ جَاہَدُوْا فِيْنَا لَـنَہْدِيَنَّہُمْ سُـبُلَنَا۰ۭ وَاِنَّ اللہَ لَمَعَ الْمُحْسِـنِيْنَ۶۹ (العنکبوت ۲۹:۶۹) جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انھیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکو کاروں ہی کے ساتھ ہے۔
جنھوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، مصیتیں اٹھائیں، ان کے متعلق کہا گیا:
فَاٰتٰىھُمُ اللہُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَۃِ۰ۭ وَاللہُ يُحِبُّ الْمُحْسِـنِيْنَ۱۴۸ (اٰل عمرٰن۳:۱۴۸) آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثوابِ آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ(محسنین) پسند ہیں۔
اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلہِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَھُمُ الْقَرْحُ۰ۭۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْھُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ۱۷۲ۚ (اٰل عمرٰن۳:۱۷۲) ن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا اُن میں جو اشخاص نیکوکار(احسان والے) اور پرہیزگار ہیں اُن کے لیے بڑا اجر ہے۔
وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللہِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّہْلُكَۃِ۰ۚۖۛ وَاَحْسِنُوْا۰ۚۛ اِنَّ اللہَ يُحِبُّ الْمُحْسِـنِيْنَ۱۹۵ (البقرۃ ۲:۱۹۵) اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیا ر کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔
سیاق وسباق کے مطابق اس جگہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی سعی و جہد میں مالی قربانیاں کرنا ہے۔
• انبیا ؑ جن کی زندگیاں دین کی دعوت اور اس کی خاطر قربانیوں میں گزریں اور جنھیں جھٹلایا گیا، ان کا ذکر محسنین کہہ کر کیا گیا:
وَوَہَبْنَا لَہٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ۰ۭ كُلًّا ہَدَيْنَا۰ۚ وَنُوْحًا ہَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِہٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰي وَہٰرُوْنَ۰ۭ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِـنِيْنَ۸۴ ﴿(الانعام۶:۸۴) پھر ہم نے ابراہیمؑ کو اسحاقؑ اور یعقوبؑ جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہِ راست دکھائی (وہی راہِ راست جو) اس سے پہلے نوحؑ کو دکھائی تھی۔ اور اُسی کی نسل سے ہم نے داؤدؑ، سلیمانؑ، ایوبؑ، یوسفؑ، موسٰی اور ہارونؑ کو (ہدایت بخشی)۔ اِس طرح ہم نیکو کاروں(محسنین) کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔
ان کے قصوں کے بعد بھی قرآن میں آٹھ مرتبہ کہا گیاکہ ہم محسنین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔
ایرانی نژاد امریکی محقق ولی نصر کی تازہ کتاب کا عنوان ہے: ’ایران کی عظیم ترین اسٹرے ٹیجی‘۔ اس کتاب میں انھوں نے ایرانی انقلاب کے مرشد علی خامنہ ای کی ایک گفتگو نقل کی ہے۔ ایرانی سیاست دانوں، دفاعی افسروں اور فقہا کے سامنے انھوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا: ’’ایران اپنے ’اسٹر یٹی جیکل‘ اہداف کی منزل پر پہنچنے کے قریب ہوچکا ہے۔ اس نے بہت سی بلندیاں سر کرلی ہیں اور پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے بالکل قریب ہے۔ چڑھائی کے اس سفر کو اسے ہر حال میں جاری رکھنا ہوگا۔ اس سفر میں تھکن کے احساس سے بچنا ہوگا۔ یاد رہے کہ وہ اس پہاڑ کی آخری چوٹی سے جس قدر قریب ہوگا، امریکا اس کے راستے بند کرنے کی اتنی ہی زیادہ کوشش کرے گا‘‘۔
ولی نصر نے اپنی کتاب میں ایرانیوں کی نفسیات کے حوالے سے جا بجا اپنے خیالات پیش کیے ہیں، لیکن اس وقت ہماری دلچسپی ایرانی مرشد کی مذکو رہ گفتگو کی مجازی تعبیر سے ہے۔ یعنی ایران کا یہ عزم کہ اسے پہاڑ کی چوٹی سر کرنی ہے اور امریکا کی یہ ضد کہ ایران کو چوٹی تک پہنچنے نہیں دینا ہے۔
اس مضمون میں ہم پہاڑ کی چوٹی کو لے کر ایران اور اس کے امریکی و اسرائیلی حریف کے درمیان کش مکش کا منظرنامہ دیکھیں گے۔ اس سے ہمیں ایران کے خلاف اسرائیل کی جاری جنگ کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے ماضی کا پس منظر، اس کے حال کی راہیں اور اس کا ممکنہ انجام۔ یہ جنگ عالم اسلام کے ملکوں اور قوموں کے مستقبل پر سالہاسال کے لیے گہرے نقوش چھوڑنے والی ہے۔
خامنہ ای نے جس مبہم مجازی تعبیر کا استعمال کیا، دوسروں نے اسے بے لاگ علمی زبان میں کھول دیا ہے۔ متعدد عرب اور مغربی جوہری ماہرین نے واضح کیا ہے کہ ایران ایٹمی طاقت بن جانے کی چوکھٹ پر پہنچ چکا ہے۔ اب محض اتنی دوری رہ گئی ہے کہ سیاسی فیصلہ اور آخری ٹیکنیکل اقدامات۔
بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ایٹمی چوکھٹ تک پہنچ جانا ہی ایران کے خلاف اسرائیلی امریکی جنگ کا حقیقی سبب ہے، جس کے پیش نظر یہ ہے کہ ایران کو پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے نہ دیا جائے۔
واضح رہے کہ خامنہ ای نے ایران کی اٹھان اور قوت کے سامنے جس امریکی رکاوٹ کا ذکر کیا ہے، وہ ایران تک منحصر نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا منظر نامہ ہے جو ایران سے آگے بڑھ کر خطے کے تمام اہمیت کے حامل ملکوں تک پہنچنے والا ہے۔
حالیہ جنگ ایک مستقل امریکی اسرائیلی اسٹرے ٹیجی کا حصہ ہے۔ حکمت عملی یہ ہے کہ کسی مسلم ملک کو، خاص طور سے مشرق وسطیٰ میں ہرمسلم ملک کو بڑی قوت حاصل کرنے یا اسٹرے ٹیجک دفاعی قوت تشکیل دینے سے باز رکھا جائے۔ ایران کے موجودہ صدر مسعود بزشکیان نے یہی بات ان لفظوں میں کہہ دی: ’’اسرائیل کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ایک ایک کرکے نشانہ بنائے‘‘۔
ایران اور خطے کے دیگر ملکوں کو یہ اسرائیلی امریکی کوشش بہت مدت پہلے سمجھ لینی چاہیے تھی اور خطے کے لوگوں کی مشترک الجھنوں اور فکرمندیوں کو دیکھنے کے زاویے وسیع تر کرلینے چاہئیں تھے، جو زیادہ وسیع الظرفی، زیادہ انصاف پسندی، زیادہ گہرائی اور زیادہ سچائی پر مشتمل ہوتے۔
امریکی اور اسرائیلی پالیسی خطے کے تمام اہم ممالک کو نشانہ بناتی ہے اور اس کے لیے اس کے طریق کار دو طرح کے ہیں: ایک طریقہ ’کنارے لگادینے ‘اور دوسرا طریقہ ’ٹھکانے لگادینے‘ کا ہے۔
’کنارے لگانے‘ کا طریقہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے امکانات کو ضائع کردیا جائے۔ یہ استعماری طریقوں کا ہی انداز ہے جو امریکا نے برطانوی سلطنت سے وراثت میں پایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خطے کے ملکوں کو اسٹرے ٹیجک فیصلوں کی خود مختاری اور اسٹرے ٹیجک قوت کی تعمیر سے محروم کردیا جاتا ہے۔ اس کے لیے حکم راں باڈی اور فیصلہ ساز اداروں میں نقب لگائی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ ملک شعوری یا غیرشعوری طور پر امریکی اسرائیلی محور پر چکر کاٹنے لگتے ہیں۔ اپنے ارادے اور موقف میں وہ سلبی ہوجاتے ہیں۔ وہ پورے طور پر غیر محفوظ ہوجاتے ہیں، خواہ ان کا حجم کتنا ہی بڑا اور ان میں موجود قوت کتنی ہی زیادہ ہو۔
اس کے لیے مختصر ترین راستہ یہ ہے کہ ریاست کے داخلی اُمور میں چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اقتدار تک صرف وہی پہنچے جو ہر طرح سے سرنگوں ہوچکا ہو، رضاکارانہ غلامی پر راضی ہوگیا ہو اور دینی، قومی اور وطنی عزت کے احساس سے دست بردار ہوچکا ہو۔ اگرچہ اسے اس کی اجازت حاصل ہو کہ عملی اقدام کے بجائے خالی کھوکھلے نعرے لگاتا رہے۔ امریکا متعدد عرب ملکوں کو کنارے لگانے اور ان کے امکانات رائیگاں کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔
’ٹھکانے لگانے‘ کا راستہ دراصل ملکوں کی عمارت ڈھادینے اور اس کے ستون ہلادینے کا عمل ہے۔ اس طریقے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ملک اطاعت گزاری کے قلادے کو اتار پھینکیں اور اپنی خود مختاری پر اصرار کریں یا جن کے عوام اپنے ملک میں آزادی اور جمہوریت کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کریں، ان کے ڈھانچے کو سلامت نہ رہنے دیا جائے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے۔
ٹھکانے لگادینے اور طاقت چور چور کردینے سے مذکورہ ملک اسٹرے ٹیجک اُمور سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی کہ اس پر حکومت کون کررہا ہے؟ وہ امریکی اسرائیلی بالادستی کا دست نگر ہے یا اس سے باہر ہے؟ کیوں کہ وہ ہر دو حالت میں بے زور اور بے وزن ہوتا ہے۔ امریکی اسرائیلی اسٹرےٹیجی اس طریق کار کو خطے کے ان بہت سے ملکوں پر آزماچکی ہے، جن کے عوام اس قلادے سے سیاسی یا عسکری طور سے باہر نکلنے لگے۔ ان میں عراق، شام، لیبیا اور سوڈان کا نام لیا جاسکتا ہے۔
’ٹھکانے لگادینا‘ کا یہ راستہ انقلابات اور عوامی فسادات کے حالات میں سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کش مکش کے نتیجے میں جو دراڑیں پڑتی ہیں، ان میں داخل ہوکر باہم متحارب تمام گروہوں کو تباہ ہونے اور تباہ کرنے کے سامان فراہم کیے جاتے ہیں، ساتھ ہی معرکے کو فیصل کرنے سے ہر فریق کو محروم رکھا جاتا ہے۔ اس طرح یہ خونی بھٹی دہکتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ملک کی طاقت پارہ پارہ ہوجاتی ہے۔ اس کے سارے کل پرزے کھل کر الگ الگ ہوجاتے ہیں، اور طاقت کے حساب کتاب سے وہ ملک بالکل باہر ہوجاتا ہے۔
لیکن ایران اور عرب ممالک صحیح وقت پر یہ ادراک نہیں کرسکے کہ امریکی اور اسرائیلی ان دونوں طریقوں سے اس خطے کو سرنگوں کرنے اور اس کی اقوام کے مستقبل کے فیصلے اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے کس طرح سوچتے ہیں؟ ان سبھی نے سادگی اور خود غرضی کے ساتھ یہ تصور کرلیا کہ وہ اپنے بھائی اور پڑوسی کی لاش کے ٹکڑوں پر شان و شوکت کی عمارت تعمیر کرسکتا ہے۔ اس طرح انھوں نے شب خون مارنے والے ہر دشمن کے لیے اس کا کام آسان کردیا۔ وہ مشترک انجام اور مشترک دشمن کی طرف کبھی کبھار ہی دیکھتے ہیں۔ یہ شعور بھی سرسری سا ہوتا ہے اور وہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب وقت گزرجاتا ہے۔ زیادہ تر یہ عین جنگ کی حالت میں ہوتا ہے، جب سر پر کلہاڑی پڑچکی ہوتی ہے۔ ۱۹۹۱ء اور ۲۰۰۳ء میں جب عراق پر تباہ کن امریکی فوج کشی ہوئی تو عراق کے حکمرانوں پر شعور کی یہ کیفیت طاری ہوئی تھی اور حالیہ اسرائیلی جنگ کے دوران ایران کے حکمرانوں پر یہ کیفیت طاری ہے۔ لیکن جب بات سمجھنے میں دیر ہوجاتی ہے تو اس کی قیمت بھی بہت بھاری چکانی پڑتی ہے۔
امریکی یہودی مفکر ایڈورڈ لوٹواک نے ۱۹۹۹ء میں شائع ہونے والے ایک مشہور مضمون ’جنگ کو موقع دینے کا نظریہ‘ کے تحت ایک طریق کار وضع کیا۔ انھوں نے اس مضمون میں اس بات کی وکالت کی کہ اس خطے میں جنگوں کے خاتمے کے لیے مداخلت نہ کی جائے، بلکہ انھیں خوںریزی کے اپنے راستے پر چلنے دیا جائے اور پھر متحارب فریقین کی طاقتیں ختم ہوجانے کے بعد آگے بڑھ کر ایک امریکی (مراد اسرائیلی) حل کو نافذ کیا جائے۔
۲۰۱۴ء میں، لوٹواک نے نیو یارک ٹائمز میں ایک مضمون میں اپنے نظریہ کو شام کی جنگ پر لاگو کرنے کی دعوت دی، جس کا عنوان تھا:’’شام میں امریکا کی ہار ہوگی، اگر کسی بھی فریق کی فتح ہوجاتی ہے‘‘۔ اس میں لوٹواک نے لکھا: ’’اس مرحلے پر طویل مدت تک توانائی خرچ کرانا ہی اس تنازعے کا واحد راستہ ہے، جو امریکی مفادات کو نقصان نہیں پہنچاتا‘‘۔ پھر انھوں نے امریکی فیصلہ سازوں کے لیے ایک نصیحت کرتے ہوئے کہا:’’جب بھی یہ ظاہر ہو کہ مسٹر بشار اسد کی افواج کی طاقت بڑھ رہی ہے تو مزاحمت کاروں کو اسلحہ فراہم کریں، اور جب یہ ظاہر ہو کہ مزاحمت کار جنگ جیتنے والے ہیں تو ان کی حمایت روک دیں‘‘۔
لوٹوا ك نے امریکی انتظامیہ کو یہ حکمت عملی اپنانے کا محض مشورہ ہی نہیں دیا، بلکہ اس نے اپنے مضمون میں یہ بھی یقین کے ساتھ کہا اور غلط نہیں کہا کہ جو کچھ اس نے تجویز کیا ہے وہی دراصل شام میں امریکا کا موقف ہے۔ یہ موقف ایک قدیم چینی حکمت عملی پر مبنی ہے کہ ’’جلتے ہوئے گھر کو لوٹ لینا چاہیے‘‘۔ مگر امریکیوں نے اس چینی نصیحت سے آگے بڑھ کر ’’گھر کو لوٹنے سے پہلے اسے جلادو‘‘ پر عمل کیا۔ شام کا دردناک بحران صرف اس لیے طویل ہوا کیوں کہ امریکی حکمت عملی ’جنگ کو موقع دینے‘ کی تھی۔ یہ حکمت عملی اسرائیلی برتری کے حصول اور امریکی اثر و رسوخ کو مستحکم کرنے کے لیے تھی، اور یہ دونوں کام دراصل تسلط، ظلم، اور جارحیت کے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔
ٹھکانے لگانے کے طریقے کبھی یکبارگی اور کبھی قسطوں میں انجام دیے جاتے ہیں۔ جب علاقے کے لوگ اپنی سیاسی بے وقوفی، سیاسی خود غرضی اور سنگین خطرات کے ادراک میں کم نظری کے باعث خود اپنے خلاف دشمن کی مدد کرتے ہیں، تو عام طور سے قسطوں والا طریقۂ کار اختیار کیا جاتا ہے، جیسا کہ ۱۹۸۰ء میں عراقی حملے کے دوران ایران اور ۲۰۱۵ء میں ایرانی حملے کے دوران شام میں ہوا، اور جس کے نتیجے میں علاقے کے متعدد ممالک اور عوام پر تلخ اثرات مرتب ہوئے۔
بعض اوقات، ٹھکانے لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماضی کے زخموں کو چھیڑا جائے، تاریخی، قومی اور فرقہ وارانہ مظاہر کے ذریعے قوم میں موجود ساختی دراڑوں کا فائدہ اٹھایا جائے۔ ان بے وقوفوں اور نادانوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے، جن کا دیرینہ شوق یہ ہوتا ہے کہ زمانہ حال میں ماضی کی جنگیں لڑی جائیں اور جن کا محبوب مشغلہ مفکر محمد احمری کے الفاظ میں: ’’گڑے مُردے اُکھاڑنا اور زندوں کو موت کے گھاٹ اتارنا‘‘ ہے۔
تقریباً ۴۵ برس پہلے، اکتوبر ۱۹۸۰ء میں، رونالڈ ریگن نے، جو اُس وقت ریپبلکن پارٹی کے صدارتی اُمیدوار تھے، اپنے دوست ہنری کسنجر سے ملاقات کی اور اس سے مشورہ کیا کہ صدارتی انتخاب میں کامیاب ہوجانے کی صورت میں ان کی خارجہ پالیسیاں کیا ہونی چاہئیں؟ اُس دن ریگن کے ذہن میں ایک اہم سوال یہ تھا کہ عراق-ایران جنگ کے بارے میں امریکا کی حکمت عملی کیسی ہونی چاہیے؟ کسنجر نے سرد مہری سے جواب دیا: ’’امریکی مفاد یہ ہے کہ عراق-ایران جنگ جاری رہے، اس لیے تمھاری کوشش یہ رہنی چاہیے کہ دونوں ممالک کے درمیان لڑائی جاری رہے‘‘۔
اس تباہ کن جنگ کے دوران، جس کی بھاری قیمت آج بھی پورے خطے کو چکانی پڑ رہی ہے، ریگن اور بعد میں جمی کارٹر بھی اس جہنمی مشورے پر عمل پیرا رہے۔ اس کے نتیجے میں، امریکی حکومت ایران اور عراق دونوں کو لڑائی جاری رکھنے کا سامان فراہم کرتی رہی اور دونوں ہی کو جنگ ختم کرنے اور اپنے عوام کے لیے اس مہلک خوںریز بھٹی سے باہر نکلنے سے روکے رکھا۔
عراق ایران جنگ کے دوران عراقی فوج کے چیف لیفٹیننٹ جنرل نزار خزرجی نے یہ بات نوٹ کی کہ عراق اور ایران کس طرح اسرائیل کو فائدہ پہنچاتے ہوئے ایک گہری کھائی میں گرگئے ہیں۔ انھوں نے اسے ’ایک تاریک سرنگ‘ قرار دیا جو عراق کے لیے تیار کی گئی تھی، تاکہ وہ ایک طویل تھکادینے والی جنگ میں پھنس جائے، جس کے دو مقاصد تھے: ایک تو عراق کی برتر قوت کو غیر مؤثر کرنا، جو اسرائیلی دشمن کے مقابلے میں ایک اہم عنصر تھا، اور دوسری طرف، جنگ کو جاری رہنے دینا تاکہ وہ جنگ میں شامل دونوں ملکوں سے بھاری ٹیکس وصول کرتی رہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں متحارب ملکوں کو کمزور کرنا اور ان کا بندوبست کرنا بھی اس جارح ریاست کے مفاد میں تھا۔ (بہ حوالہ: نزار خزرجي، ’مذکرات مقاتل، جنگ جو کی ڈائری‘)
’بتدریج ٹھکانے لگانے‘ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خطے کے فریقوں میں سے کسی ایک فریق اور امت کے اجزا میں سے کسی ایک جزو کو نشانہ بنایا جائے اور اس طرح خطے کی اقوام اور امت کے اجزا کے درمیان باہمی تعاون کے احساس کو ماؤف کردیا جائے۔ نوّے کے عشرے میں برسہابرس عراق کو تباہ کرنا اور اسے لمبے حصار سے دوچار رکھنا، پھر ۲۰۰۳ء کی ابتدا سے اس پر قابض ہوجانا اور اسے ٹھکانے لگادینا، اس کی تلخ مگر کلاسیکل مثال ہے۔
ان عمومی تمہیدی کلمات کے بعد، ہم حالیہ جنگ کی ماہیت اور نتائج کے حوالے سے تجزیے کی کوشش کریں گے۔ حالیہ جنگ کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں زیادہ وسیع سیاق میں اسے رکھنا چاہیے۔ بیرونی مداخلت کی حالیہ صورت حال بھی سامنے رکھیں گے اور عام اسٹرے ٹیجک ماحول پر ’طوفان اقصیٰ‘ کے اثرات کو بھی پیش نظر رکھیں گے۔
اس خطے میں امریکا کے حصے میں برطانوی فوجی استعمار کی وراثت آئی۔ اس نے اسے سیاسی اور ’اسٹر یٹی جیکل‘ استعمار میں تبدیل کردیا جو لمبی مدت تک اسے پھل دیتا رہے۔ آج اسرائیل کے عزائم یہ ہیں کہ امریکی سیاسی استعمار اسے وراثت میں مل جائے۔ ویسے بھی امریکا خطے کے بوجھ کو کم کرنے اور اپنی سرحدوں تک سمٹ جانے، نیز مشرقی ایشیا میں چین کے ساتھ بڑی کش مکش پر توجہ مرکوز کرنے کی طرف پیش قدمی کررہا ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جنگ کو ان اسرائیلی عزائم سے الگ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو اسرائیل، ایران کے معاملے میں اسے جوہری طاقت سے باز رکھنے کی پالیسی پر اکتفا کرتا۔
لیکن ایک طرف تو اسرائیل، برطانیہ عظمیٰ یا امریکا جیسی طاقت کا مالک نہیں ہے، دوسری طرف یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس میں ان دونوں ملکوں کی بالادستی تھی۔ اس لیے اسرائیلی اسٹرے ٹیجی، جسے امریکا کی پشت پناہی حاصل ہے، خطّے کے بعض لیڈروں کی رضاکارانہ غلامی پر انحصار کرتی ہے۔ یہ لیڈر قدیم دور کے 'استعماری قافلوں کے ہراول دستے بننے کا شوق رکھتے ہیں، حالاں کہ انھیں اس کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔
لیکن یہ غلامی کا شیوہ ہے، یا ابن خلدون کی اصطلاح میں ’سرفگندگی اور حوالگی کا مذہب‘ ہے۔ حالیہ برسوں میں کچھ عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ پورے ’ایمان واخلاص‘ کے ساتھ نارملائزیشن کے معاہدوں پر دستخط کیے، حالاں کہ نہ تو اسرائیل سے ان کی کوئی کش مکش تھی اور نہ ان کی سرحدیں اسرائیل سے ملتی تھیں۔ ایسے معاہدوں پر ابن خلدون کا مذکورہ بالا قول پوری طرح صادق آتا ہے۔
اس طرح ان عرب ملکوں نے اسرائیل کی گود میں مفت کی کامیابیاں لاکر ڈال دیں، جس سے اس کی نرگسیت بڑھ گئی اور اس کا دماغ آسمان پر پہنچ گیا۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ سے دراصل اس خطے میں جو اسٹرے ٹیجک خلا پیدا ہوگیا ہے، اسے بھرنے کے اسرائیلی عزائم کی طرف پیش قدمی ہے۔ دوسری طرف اس خطے کے لوگوں نے اپنے لیے یہ پسند کرلیا ہے کہ وہ دائمی کمزوری اور نقاہت کی حالت میں رہیں۔
حالیہ جنگ کے آغاز میں سب سے پہلے امریکا کے مبہم اور فریب کار کردار کی طرف نگاہ جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکا کا فیصلہ تو عرصے سے جنگ کے حق میں تھا، لیکن امریکیوں نے اسرائیلیوں کے ساتھ یہ طے کرلیا تھا کہ امریکا شروع میں ذرا پیچھے اور فاصلے پر رہے گا، امداد پر اکتفا کرے گا، ایران کو دھوکا دے کر غفلت میں رکھے گا، یہاں تک کہ اسرائیل اچانک اس پر پہلی ضرب لگانے کی پوزیشن میں آجائے۔
امریکی صدر ٹرمپ نے اس میدان میں بھرپور اداکاری کی۔ اس نے ایرانیوں کو یہ اطمینان دلایا کہ وہ ان کے ساتھ ایک نیا ایٹمی معاہدہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہے، اور خوش گمانی اور لچک کا مصنوعی ماحول بناکر انھیں سُن کردیا۔ یہ بات واضح ہے کہ ایرانی غفلت کے جال میں پھنس گئے۔ پہلی اسرائیلی ضرب کے وقت ان کی طرف سے کسی تیاری کا اظہار نہیں ہوا اور اسی لیے وہ اپنے بہترین اعلیٰ فوجی افسران اور شان دار ایٹمی سائنس دانوں سے ہاتھ دھوبیٹھے۔
ایران کے خلاف اسرائیلی جنگ کا ’طوفان اقصیٰ‘ سے گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ ملٹری سائنس میں کہا جاتا ہے کہ ’’ہر جنگ کے کچھ غیر مطلوبہ ثمرات بھی ہوتے ہیں جو مطلوب ثمرات سے کبھی زیادہ بھی ہوجاتے ہیں‘‘۔ ’طوفان اقصیٰ‘ کے دو ثمرات کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ اسٹرے ٹیجک اہمیت کے پہلو سے وہ مطلوب ثمرات سے بڑھ کر ہیں: ایک بشار اسد سے ملک شام کو آزادی مل جانا اور دوسرا اسرائیل اور ایران کے درمیان حالیہ جنگ کا بھڑک جانا۔
شہید عظیم یحییٰ سنوار کو توقع تھی کہ ’طوفان اقصیٰ‘ فلسطین کے گردوپیش کے اسٹرے ٹیجک ماحول میں گہری تبدیلی پیدا کرے گا۔ جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ایران کی اسرائیل کے ساتھ راست مڈبھیڑ ہوگی۔ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس معاملے میں ان کا اندازہ بالکل درست تھا۔ حالاں کہ میں نے بھی اور بہت سے دوسرے افراد نے بھی اسے بظاہر دور کا خواب سمجھا تھا۔
بہرحال، اچانک کیا جانے والا پہلا حملہ اگر کامیاب بھی ہوجائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جنگ بھی جیت لی گئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جاپان نے ’پرل ہاربر‘ کے مہلک حملے کے بعد امریکا کو شکست دے دی ہوتی۔ اسرائیل نے اپنی پہلی کامیاب کارروائی کا زیادہ لطف نہیں اٹھایا ۔ حالانکہ وہ ایران کے لیے تکلیف دہ تھی اور جلد ہی اس حملے کا جواب اور ردعمل شروع ہوگیا۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ اسرائیل کا غیر متوقع حملہ اور اس کے بعد کے حملے، ایرانی جوہری پروگرام کے مرکز تک پہنچنے میں ناکام رہے، خاص طور پر ’فوردو‘ کی محفوظ تنصیبات جو پہاڑ کے قلب میں واقع ہیں، اور ایران کے افزودہ یورینیم کا ذخیرہ۔
اب ہم جنگ کی درپیش راہوں کا اندازہ کرسکتے ہیں جو بہرحال تقریباً غیر یقینی ہوگا۔ وقت کے گزرتے واقعات کی تبدیلی سے یہ تصور تبدیل بھی ہوسکتا ہے۔ ہر جنگ اپنے طریقے سے مختلف پیچ و خم سے گزرتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی راہوں اور نتیجوں کا تعین کیا جاسکے۔ کیوں کہ ایسے عوامل درپیش ہوسکتے ہیں، جن کا شروع میں منصوبہ بندی کے وقت خیال تک نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال، اس جنگ کی اب تک جن راہوں کا تصور کیا جاسکا ہے، وہ حسب ذیل ہیں:
ایٹمی اور میزائل ٹکنالوجی میں سرمایہ کاری ہی ایرانی اسٹرے ٹیجی کا کل سرمایہ ہے۔ یہ کوئی ثانوی چیز نہیں ہے، جس سے دست بردار ہونا آسان ہو۔
ایران کی سیاسی اشرافیہ امریکا پر بھروسا نہیں کرتی ہے۔ وہ کسی بھی حالت میں اپنی گردن حوالے نہیں کرے گی، خواہ اسے کسی بڑی طاقت کے ساتھ وجودی جنگ میں اترنا پڑجائے۔
اس راہ میں ہوسکتا ہے کہ ایران اعلان کردے کہ وہ یورینیم کی افزودگی سے دست بردار ہونے کو تیار ہے، لیکن اپنے ایٹمی اور میزائل پروگرام سے دست بردار نہ ہو۔ اس کے بدلے امریکا جنگ روک دے۔ وہ امریکا اور اس کے حلیفوں کے ساتھ اس مضمون کا نیا ایٹمی معاہدہ کرلے۔ پھر مستقبل میں چپکے سے ایک خفیہ ایٹمی پروگرام کو برقرار رکھے، یہاں تک کہ ایٹمی طاقت بننے کا اس کا خواب پورا ہوجائے۔
یہ راہ بھی قابلِ عمل نہیں لگتی ہے۔ کیوں کہ امریکا اور اسرائیل اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے، جب تک ایرانی بالادستی کو پامال کرکے تحقیق وتفتیش کے نام پر اس کی سرزمین کے ہرراستے میں داخل نہ ہوجائیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے عراق میں ہوا۔ جب کہ ایرانی قیادت اس کے لیے ہرگز آمادہ نہیں ہوگی کہ وہ سیکوریٹی، فوجی اور سیاسی، ہر پہلو سے سامنے آجائے اور بالکل غیرمحفوظ ہوجائے۔
یہ راہ ممکن اور قابلِ عمل ہے۔ یہ خیال ڈاکٹر یسری ابوشادی کا ہے جو بین الاقوامی ایجنسی برائے ایٹمی توانائی کے تفتیش کاروں کے سابق صدر ہیں۔ انھوں نے اپنے سائنسی تجربے اور ایران کے ایٹمی پروگرام سے آگہی کی بنا پر یقین کے ساتھ کہا کہ ایران کم افزودہ یورینیم سے ایک سے دوہفتے کے اندر ایٹم بم بناسکتا ہے۔
ایٹم بم کے ٹیسٹ کے لیے اس کے پاس سائنسی تجربہ، ٹیکنیکل استعداد اور مناسب جگہیں میسر ہیں۔ رچرڈ نیفیو کولمبیا یونی ورسٹی کے محقق ہیں اور صدر بائیڈن کی حکومت میں ایرانی معاملات کے لیے مختص امریکی نمائندے کے اسسٹنٹ رہ چکے ہیں، وہ بھی اس راہ کو بعید نہیں سمجھتے۔
اس حالت میں ایران کے پاس کچھ کھونے کو نہیں بچے گا، پھر اس کا میلان جنگ کے دائرے کو بڑھانے اور آگ پھیلانے کی طرف ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے یا اپنے حلیفوں کے ذریعے وہ امریکی مفادات کو نشانہ بنائے گا اور توانائی کا عالمی بحران کھڑا کردے گا، جس سے جنگ علاقائی نہ رہ کر عالمی صورت اختیار کرلے گی۔یہاں یہ یاد دلانا اہم ہے کہ روس کے لیے ایران کی غیرمعمولی جیوپولیٹیکل اہمیت ہے اور چین کے لیے توانائی پر مبنی معاشی اہمیت ہے۔ ایران روس کی جنوبی سرحد ہے۔
دوسری طرف چین کا ایران سے ’اسٹر یٹی جیکل‘ شراکت کا معاہدہ ہے۔ وہ ایران سے اپنی ضرورت کے بڑے حصے کا پٹرول درآمد کرتا ہے۔ ایران کے خسارے یا تباہی پر خاموشی اختیار کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔
ان ممکنہ راہوں میں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ ایران روایتی ہی سہی ایٹمی طاقت حاصل کرلے۔ اس کے بعد آگ کے پھیل جانے کی راہ ہے۔ جہاں تک سرنگوں ہوجانے یا تقیہ کرنے کی راہ ہے تو وہ قابلِ عمل نہیں لگتی۔
جہاں تک عرب پڑوسیوں کی بات ہے، سب سے بہتر راہ پانچویں ہے، جس میں جلد از جلد جنگ رُک جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب ہوجائے۔ کیوں کہ خطہ میں امن وامان ہونہیں سکتا اور خلیج پر اسرائیلی بالادستی کے عزائم پر روک نہیں لگ سکتی، جب تک ایران کو ایٹمی تحفظ حاصل نہ ہوجائے۔ اس کے بعد سیاسی تقیہ کی راہ ہے، گو کہ لانگ ٹرم میں وہ قابلِ عمل نہیں ہے۔
جہاں تک آگ پھیلنے کی راہ ہے، تو وہ عرب اور مسلم پڑوسی ممالک کے لیے بہت بڑا سانحہ ہوگا اور جہاں تک ایران کے جھک جانے کی بات ہے تو اس کے نتیجے میں صہیونی طاقت کے سامنے ’سیاسی عبودیت‘ کا دروازہ کھل جائے گا اور سبھی لوگ پورے طور پر ’اسٹر یٹی جیکل‘ عدم تحفظ کا شکار ہوجائیں گے۔
حالیہ جنگ کے ایسے حالات میں مناسب تر اخلاقی اور سیاسی موقف اختیار کرنے کی کم سے کم سطح کیا ہونی چاہیے؟
مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جب بھی نئے سیاسی حالات پیدا ہوتے ہیں، اور ایران اس میں ایک فریق ہوتا ہے، تو ایران اور اس کے ماضی اور حال کی پالیسیوں اور اس کی دور و نزدیک کی تاریخ کو لے کر عربی فضا میں ایک ہنگامہ برپا ہوجاتا ہے۔
یہ ایک مشکل موضوع ہے، اس میں حق و باطل گڈمڈ ہوجاتے ہیں۔ انصاف پسندی اور عصبیت پسندی کے تقاضے باہم ٹکراتے ہیں۔ جذبات کا جوش اور اسٹرے ٹیجک حساب کتاب میں خلط مبحث ہوجاتا ہے۔ اس بحث میں سب سے بری بات یہ ہے کہ اس کی پشت پر جو یادداشت کام کرتی ہے، اس میں چھید ہوتے ہیں۔ اس مصیبت زدہ خطے میں چند برسوں پہلے جو کچھ بیتی وہ پیش نظر نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یادداشت کو تازہ کیا جائے، کچھ بھولے ہوئے بدیہی مسلّمات کو یاد دلایا جائے اور ماضی قریب سے عبرت پکڑنے کی اپیل کی جائے۔
ہم اختصار کے ساتھ اس حوالے سے پانچ باتیں پیش کریں گے:
غرض جب تمام مسلمانوں کا عمومی دشمن کسی پر حملہ آور ہو، تو ان مسلمانوں کی مدد لازم ہے۔ یہ فریضہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک وہ اصل اسلام پر باقی ہے۔ عقائد کے باریک مسائل میں اختلاف، یا سیاسی مفادات میں فرق، یہاں تک کہ امت کے افراد کے آپس کے ظلم و ستم، خواہ وہ کتنے ہی بڑے اور زیادہ ہوں، اس فریضہ پر اثر انداز نہیں ہوسکتے۔اس لیے شرعی طور پر یہ طے شدہ بات ہے کہ اس وقت اسرائیل کے مقابلے میں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا لازم ہے، خواہ وہ زبانی اور اخلاقی مدد ہی کیوں نہ ہو۔
آج اگر ایران نشانے پر ہے تو وہ محض ایران نہیں ہے اور کل جب عراق نشانے پر تھا تو محض عراق نہیں تھا۔ دراصل یہ پوری امت کو نشانہ بنانا ہے۔ امریکا اور اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ امت کی قوتِ مدافعت توڑ دی جائے اور اس کی قوت کے پوشیدہ امکانات کو ختم کردیا جائے، خواہ وہ قوت عراقی ہو یا شامی، ایرانی ہو یا ترکی یا پاکستانی۔ البتہ یہ نشانہ بازی قسط وار ہورہی ہے، تاکہ حال میں ڈوبے ہوئے اور اپنے آج سے آگے نہ دیکھ پانے والے بے وقوفوں کو غفلت کا شکار رکھا جائے۔
آج جو ایران کو نشانہ بنارہا ہے، اس کا مقصد شام، عراق یا یمن میں بہنے والے خون کا بدلہ لینا نہیں ہے، بلکہ وہ تو آج بھی اس پر بضد ہے کہ اسے ان سب کا خون بہانے اور ان سب کو ذلت و عبودیت میں باقی رکھنے کی قدرت حاصل رہے۔
اس وقت، جب کہ ایران اسرائیلی آگ کی زد میں ہے، ایران کے ساتھ پچھلے حساب چکانے کی بات کرنا، اچھی نیت ہو تو سیاسی حماقت اور بری نیت ہو تو اپنوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا اور حملہ آور دشمن کے قافلے میں شامل ہوجانا ہے۔ یہ روش اُمت کو تباہ کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔
پہلا گروہ دین، حق اور انسانیت سے آراستہ ہے اور دوسرا گروہ ان سب اوصاف سے عاری ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے کہ ایرانی رہنماؤں کو ان کی سیاسی خود غرضی، یا قومی جانب داری، یا فرقہ وارانہ عصبیت نے گم راہ کیا اور انھوں نے خطے کے اہم معاملات میں غلط موقف اختیار کیا، جیسے عراق پر فوج کشی اور شام میں انقلابی تحریک کے سلسلے میں ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے اس رویے میں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں۔ آج ایران کی آزمائش کے وقت اس کے خلاف سیاسی خود غرضی، قومی جانب داری اور فرقہ وارانہ عصبیت کا دامن تھامنا اس کے شایان شان نہیں ہے جو اللہ، اس کے رسولؐ اور مسلم اُمت کا خیر خواہ ہو۔
اور اگر کسی کے دل میں اپنی قوم کے حوالے سے ایران سے بدلہ لینے کی آگ جل رہی ہو، اور وہ اسرائیل کے خلاف ایران کی مدد کے لیے اپنے دل اور زبان کو آمادہ کرنے پر آمادہ نہ ہو، تو اس کے لیے خاموشی بہتر ہے،تاکہ وہ اس دشمن کا ہم رکاب تو نہ ہوجائے جو امت کو صفحۂ ہستی سے مٹادینے کے درپے ہے۔
لیکن اگر وہ خاموشی سے آگے بڑھ کر اس بڑی جنگ میں ایران کی مصیبت پر خوشی منائے اور ہمت شکنی کا کام کرے تواس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ بات ہر صاحبِ بصیرت جانتا ہے کہ یہ جنگ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پورے خطے بلکہ پوری مسلم امت کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اس جنگ کے پیچھے دشمن کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے تمام ملکوں اور اقوام کی حُرمت کو پامال کرے اور مسلم امت پر یہودی بالادستی کے ایک نئے دور کو مسلط کرے۔
جس کی نگاہِ بصیرت حالات کو دیکھ رہی ہے، جو صہیونی طاقتوں کی اسٹرے ٹیجی اور ترجیحات سے آگاہ ہے، وہ بڑی آسانی سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ خدانخواستہ ایران کی شکست کی صورت میں سب سے پہلے جس کے اوپر مصیبت کے بادل گھریں گے وہ جدید ملک شام ہے۔ جو خوںخوار بشار اسد کے اقتدار سے آزاد ہوا ہے، فلسطین کی سرحدوں پر واقع ہے اور ابھرتے ہوئے ترکی کا حلیف ہے۔
اگر شام کی نئی مقتدرہ سے امریکا نے چشم پوشی سے کام لیا ہے، جب کہ اس کا حریت پسند اسلامی پس منظر ہے اور عالمی سطح پر مجاہدانہ روابط ہیں، تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ امت کے اجزا کو تباہ کرنے کے لیے ’قسط وار تباہی‘ کا طریقہ اختیار کیا جارہا ہے۔ اس میں جب ایک مخصوص حصے کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو باقی دوسرے حصوں کو الگ رکھا جاتا ہے۔ امریکا کی قدیم ’اسٹر یٹی جیکل‘ روایتوں میں سے ایک یہ ہے کہ چوڑے محاذوں پر جنگ سے اجتناب کیا جائے اور بیک وقت کئی معرکوں میں مصروف نہ ہوا جائے۔
نئے شام کے ساتھ امریکا کی جنگ بندی اس جنگ بندی سے مختلف نہیں ہے، جو امریکا نے عراق پر فوج کشی کرتے ہوئے ایران کے ساتھ کی تھی۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ چودہ سال کی طویل مدت تک صہیونی ایجنڈے کی خاطر شامی عوام کے ساتھ خونی کھلواڑ کرنے کے بعد امریکا نے سچی توبہ کرلی ہو۔
یہ درست نہیں ہوگا کہ ہم بھی ’تاخیر سے سمجھنے‘ کی اس غلطی میں پڑجائیں جس کی قیمت آج ایران ادا کررہا ہے۔ اور ہم بھی اسی مہلک گناہ کا ارتکاب کریں، جس کا ارتکاب ایران کرچکا ہے، جب اس نے امریکا کی عراق پر فوج کشی کو ایک غنیمت موقع سمجھا پڑوسی سے دشمنی نکالنے، اس کی داخلی حرمت پامال کرنے اور آزادی کے ساتھ خطے میں اپنے بازو پھیلانے کا۔ اس کا انجام وہی ہوا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے پوری امت پر واجب ہے کہ اس وقت ایران کے ساتھ کھڑی ہو اور اس کے سقوط یا بربادی کو روکنے کے لیے تمام تر کوششیں کریں۔ اگر یہ اسلام کے بنیادی محرکات کی بنا پر نہ ہو،تو بھی سیاسی حکمت، عملی مفاد اور اسٹرے ٹیجک شعور کے محرکات کی بنا پر ہی ہو۔
جیسا کہ مضمون کے شروع میں ذکر ہوا کہ ایران نے دشوار گزار راستہ اپنے لیے پسند کیا۔ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے چلتے رہنے کا عزم و جنون پالا، جب کہ دشمن کی قوت اور راستے کی وحشت بہت تھی۔ ایسے میں عالم عرب کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ پستی اور پست ہمتی کی زندگی اپنے لیے قبول کرے۔ تیونس کے شاعر ابوالقاسم شابی نے بہت خوب کہا ہے:
وَمَنْ يتهيَّبْ صعودَ الجبَـال يَعِشْ أبدَ الدَّهر بين الحُفَرْ، جو پہاڑوں کو سر کرنے سے ڈرے گا وہ زندگی بھر گڑھوں میں رہے گا۔
ایران آج قیمت ادا کررہا ہے اپنی اس ضد کی کہ وہ اپنی دفاعی قوت بنائے گا، اپنے اسٹرے ٹیجک فیصلوں میں آزاد رہے گا، قدس اور اقصیٰ کے قضیے میں مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرے گا۔ اگر وہ اس آزمائش سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہوگیا، امریکی اسرائیلی رکاوٹ پار کرگیا اور ایٹمی چوکھٹ سے گزرگیا، تو اس میں اس کا بھی فائدہ ہے اور پورے خطے کا بھی، کیوں کہ اس کے بعد امریکی اسرائیلی کالی گھٹا چھٹنے لگے گی۔
اور اگر ایران حالیہ جارحیت کے سامنے ٹوٹ پھوٹ گیا، تو پورا خطہ ’منحوس غلامی‘ کے تاریک دور میں زندگی گزارے گا۔ کواکبی نے بتایا ہے کہ جب قومیں اپنی اندرونی دراڑوں میں بیرونی لالچیوں کو گھسنے کی راہ دے دیتی ہیں، تو منحوس غلامی میں جاپڑتی ہیں۔
اسرائیل اور ایران جنگ کے خطرات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میرے ایک دانا ترکیہ دوست نے کہا: ’’ضروری ہے کہ ہم ایران کو بچائیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایران سے اپنے آپ کو بچائیں‘‘۔ پھر اس نے تفصیل سے بتایا کہ اس جنگ کے ترکیہ پر کیا منفی اثرات واقع ہوں گے۔
یہ مساوات ایران کے عربی پڑوس پر بھی صادق آتی ہے۔ اسے اس کی بھی ضرورت ہے کہ ایران کو تباہی سے بچایا جائے اور اس کی بھی ضرورت ہے کہ خود اسے مستقبل کی ایرانی حماقتوں سے بچایا جائے۔ اس جنگ سے ایران کو ایک تکلیف دہ سبق تو شاید مل ہی جائے کہ ایڈوانس ڈیفنس کا نظریہ جو پڑوسی کو اہمیت نہیں دیتا ہے، خود بھی پھنستا ہے اور سب کو پھنساتا ہے۔ ایران کی یہ اپروچ جتنی اس کے پڑوسیوں کے لیے خطرناک ہے، اس سے کہیں زیادہ خود اس کے لیے خطرناک ہے۔
بہرحال، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ایران کو ٹوٹنے سے اور آگ کو پھیلنے سے روکا جائے۔ میرے دوست عراقی محقق ڈاکٹر لقاء مکی نے ایران سے زبان و تیغ سے برسوں جنگ کی، لیکن اب انھوں نے لکھا: ایران کا معاملہ کچھ بھی ہواور خطے میں اس کا جارحانہ رویہ کیسا بھی رہا ہو، تاہم امریکی اسرائیلی گٹھ جوڑ کے ہاتھوں اس کی تباہی بہت بڑا سانحہ ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ہم سب ایک نئے دور کا سامنا کریں گے جو سوبرسوں میں سب سے زیادہ سنگین اور سب سے زیادہ الم ناک ہوگا۔
عقل مند وہ ہے جو ’نشانہ صحیح باندھے‘ اور جس وقت کا جو تقاضا ہے اسے پورا کرے۔ احمق وہ ہے، جو ماضی کو مستقبل کی بربادی کا سامان بنائے اور ناوقت اپنے پڑوسی کے سامنے اپنے عضلات کی نمائش کرے، جب کہ فریب کار دشمن چھری تیز کررہا ہو تاکہ اس کے پڑوسی کو ذبح کرنے کے بعد پھر اس کی گردن پر پھیرے‘۔
بیسویں صدی کے اوائل میں متحدہ ہندوستان میں مرحوم احمد شاہ پطرس بخاری اپنے ایک طنزیہ مضمون ’مرید پور کا پیر‘ میں رقم طراز ہیں کہ جس شہر میں وہ مقیم تھے، وہیں کانگریس نے اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی اور جب ایسا جلسہ بغل میں ہو رہا ہو، تو کون متقی وہاں جانے سے گریز کرے گا۔ یہی صورت حال کم و بیش حال ہی میں مجھے پیش آئی۔ معلوم ہوا کہ ترکیہ کے عروس البلاد استنبول میں ۵۷ ؍اراکین پر مشتمل ’اسلامی تعاون تنظیم‘ (OIC)کے وزرائے خارجہ کا اکاون واں اجلاس منعقد ہو نے والا ہے۔ اب ترکیہ میں مقیم کون صحافی اس موقعے کو ضائع ہونے دیتا۔ ایک تو خطے کی صورت حال ’ایران- اسرائیل جنگ‘، غزہ کی قتل گاہ کا المیہ، دوسرا اس کانفرنس کے دوران افریقی ملک برکینا فاسو کے وفد سے ملاقات کی طلب تھی، جس کے صدر ابراہیم ترورے نے استعماری طاقتوں کے خلاف افریقی ممالک کو متحد کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔
ترکیہ کے شہر استنبول کی داد دینی پڑے گی کہ شہر میں ستاون وزرائے خارجہ اور ان کے وفود کی موجودگی کے باوجود نہ کہیں ٹریفک میں خلل تھا اور نہ معمولات زندگی میں کوئی رخنہ۔ کانفرنس بلڈنگ تک معلوم ہی نہیں پڑا کہ شہر میں اتنی بڑی تعداد میں وی وی آئی پییز جمع ہیں ۔ کوئی سڑک بند، نہ پولیس کے دستے نظر آرہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک یا دو غیر ملکی سربراہان کی آمد پر بھی نئی دہلی میں تو کئی اہم شاہرائیں بند ہو جاتی ہیں جن سے کئی کئی کلومیٹر دُور تک ٹریفک جام لگتا تھا۔ اسلام آباد میں پچھلے سال ’شنگھائی تعاون تنظیم‘ کے اجلاس کے موقع پر تو پورا شہر ہی بند کردیا گیا تھا۔ حتیٰ کہ شہرکے نواح میں کانفرنس ہال سےبہت دُور شادی ہالوں تک کو بند رکھنے کی ہدایت دی گئی تھی۔
کانفرنس کے استقبالیہ پر معلوم ہوا کہ میرا نام فہرست میں موجود ہی نہیں تھا۔ وجہ بتانے کےلیے کوئی موجود نہیں تھا۔ دو گھنٹہ منت سماجت کرنے اور یہ دہائی دینے کے بعد کہ میں انقرہ سے بس اسی کانفرنس کو کور کرنے کےلیے چلا ہوں اور ہوٹل میں مقیم ہوں، تو اسکارٹ کرکےمجھے پریس گیلری میں لے جایا گیا، جو اسٹیج سے کافی دور اوپر کی منزل میں تھی۔ بتایا گیا کہ صرف افتتاحی سیشن ہی پریس کےلیے اوپن ہے۔ترک افسران بار بار معذرت کا اظہار کررہے تھے کہ رجسٹریشن کے باوجود او آئی سی کے سیکرٹریٹ کے اجازت نامے کی فہرست میں میرا نام کیوں نہیں تھا؟ معلوم ہوا کہ میرا بھارتی پاسپورٹ اور شہریت دیکھ کر آو آئی سی سیکرٹریٹ نے میرا نام فہرست میں شامل نہیں کیا تھا۔ ان کو ہدایت تھی کہ بھارتی اور اسرائیلی صحافیوں کو اس کانفرنس تک رسائی نہیں دینی ہے۔
افتتاحی سیشن سے ترک صدر رجب طیب ایردوان نے خطاب کیا۔ اس کے بعد صحافیوں کو دوسری بلڈنگ میں میڈیا سینٹر لے جایا اور بتایا گیا کہ اب کانفرنس کی جائے وقو ع تک ان کی رسائی بند ہے۔ یہ ایک نئی روایت ہے۔ پچھلے تیس برسوں سے سارک سربراہ یا وزرائے خارجہ کانفرنس، ناوابستہ ممالک کا اجلاس،برکس، شنگھائی تعاون تنظیم، افریقہ چوٹی اجلاس یا اقوام متحدہ کی ماحولیات سے متعلق وغیرہ ایسی اَن گنت کانفرنسیں کور کرنے کا موقع ملا ہے۔ ان میں ایک یا دو سیشن آن ریکارڈ میڈیا کےلیے کھول دیئے جاتےتھے، مگر پھر صحافی وہیں بلڈنگ کے آس پاس یا لابی وغیر میں ہی گھومتے پھرتے تھے، اور مہمان بھی ناشتے، لنچ کے وقت ان سے مل لیتے تھے۔ اس طرح جب صحافیوں کا کانفرنس کے مندوبین کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا تھا، تو خبرو ں کے حصول کے علاوہ ان کے شعور اور عالمی امور کی سوجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا تھا اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی تھی۔
صحافیوں کےلیے یہ اب ایک سنجیدہ معاملہ بن چکا ہے۔پوری دنیا میں مسند ِحکومت پر فائز افراد کو لگتا ہے کہ اب ان کو میڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نے ان کی رسائی عوام تک براہِ راست کر دی ہے۔ اس لیے میڈیا کو اب رسمی یا غیر رسمی رسائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس صورتِ حال میں صحافیوں کی موجودہ نسل کو علمی مہارت یا تجزیہ کاری کا تجربہ حاصل ہو تو کیسے ہو؟ خود صحافیوں نے بھی اس خرابی میں اضافہ کیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے بس مائیک اور کیمرہ رپورٹروں کو کسی مندوب کے آگے کرکے بریکنگ نیوز لانی ہوتی ہے۔ اس پر خاصے جھگڑے بھی ہوتے تھے، اسی وجہ سے رسائی بند کر دی گئی ہے۔ انفارمیشن حاصل کرنے کےلیے ایک غیر رسمی بریفنگ اور انٹر ایکشن کا ہونا ضروری ہے، جو بعد میں مضامین یا اداریوں میں جھلکتا ہے۔ ورنہ وہی حال ہوگا، جس کا مظاہرہ حال کی ’انڈیا-پاکستان جنگ‘ میں انڈین میڈیا خاص طور پر ٹی وی چینل کر چکے ہیں۔
کانفرنس کے پہلے روز کے اختتام کے فوراً بعد ہی امریکا نے ایران پر حملہ کرکے اس کی نوعیت ہی بدل دی۔ اگلے روز ایرانی وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اپنا دورہ ادھورا چھوڑ کر صلاح و مشورہ کےلیے ماسکو چلے گئے۔ چونکہ شام کی جنگ میں ایران نے روس کی خاصی مدد کی تھی اور مشرق وسطیٰ میں ایک عرصے کے بعد روس کو قدم جمانے اور بحری اڈہ قائم کرنے میں مدد کی تھی، اس لیے ایران کو اُمید تھی کہ روس اس احسان کا کچھ بدلہ تو ضرور چکائے گا۔
اس کانفرنس کے دوران احساس ہوا کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک مدت تک مسلم ممالک کی قیادت پر فائز رہے تھے،کئی عشرے قبل ایک بڑی تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ مسلم ممالک کی سربراہی آہستہ آہستہ پاکستان اور سعودی عرب کے ہاتھوں سے نکل کر ترکیہ اور ایران کے پاس چلی گئی۔ جب سے او آئی سی کا قیام عمل میں آیا، تب سے ہی پاکستان میں وزارت خارجہ کی نکیل چونکہ ذولفقار علی بھٹو سے لے کر شاہ محمود قریشی بشمول صاحب زادہ یعقوب خان وغیر جیسے زیرک اور انگریزی جاننے والے افراد کے ہاتھوں میں ہوتی تھی، اس لیے کانفرنس کا ایجنڈا اور اعلامیہ اکثر وہی ڈرافٹ کرتے تھے۔ سعودی عرب میں اس تنظیم کا سیکرٹریٹ تھا اور مالی طور پر سب سے زیادہ بار وہی اٹھاتا تھا۔ اس لیے ان دو ملکوں کا رُتبہ اسلامی تنظیم میں وہی تھا، جو اقوام متحدہ میں امریکا اور سوویت یونین کا ہوتا تھا۔ مگر تین عشرے قبل آہستہ آہستہ پاکستان اس تنظیم کےلیے غیر متعلق ہوتا گیا اور یہ منصب ترکیہ کے پاس آتا گیا، جو اس دوران خاصا فعال ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایردوان کی حکومت آنے کے بعد یہ رول زیادہ بڑھ گیا۔
سعودی عرب خود قیادت کے منصب سے پیچھے ہٹتا گیا، جس کا خاطر خواہ فائدہ قطر، متحدہ عرب امارات، ملایشیا اور ایران کو حاصل ہوا۔ نظریاتی وجوہ کی بناکر ایران کا رول محدود رہا مگر اس نے لیڈرشپ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ موجودہ حالات میں خاص طور پر انڈیا کے ساتھ محدود جنگ میں ہارڈ پاور کا استعمال کرکے پاکستان کے لیے قیادت کا منصب پھر استوار ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ایران کا کردار بھی بڑھ گیا ہے۔ اس کانفرنس میں محسوس ہوا کہ سعودی عرب قیادت کے منصب کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ عرب ممالک میں قطر اور افریقی ممالک میں برکینا فاسو اس بار بہت ہی سرگرم تھے۔
کانفرنس کے دوسرے دن جب خاصی تگ و دو کے بعد اعلامیہ جاری ہوا، تو مایوس کن بات یہ تھی، کہ اس میں ایران پر اسرائیل کے حملوں کا تو ذکر تھا، مگر امریکا کا کہیں نام شامل نہیں تھا۔ ۵۷ ممالک میں کوئی بھی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ناراضی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ پاکستان کی افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر، صدر ٹرمپ کے ساتھ اپنی ملاقات کے بعد ایردوان کو بریف کرنے پہنچ گئے تھے اور انھوں نے بھی افتتاحی سیشن میں شرکت کی۔
ایک اہم انکشاف یہ تھا کہ مسلم دنیا میں اب یہ سوچ پنپ رہی ہے کہ طاقت اب صرف سیاست اور احتجاج میں نہیں، بلکہ تعلیم، ابلاغ اور ادارہ جاتی صلاحیت میں بھی پنہاں ہے۔ اس کانفرنس میں استنبول میں ہی ایک ’میڈیا فورم‘ کے قیام کی منظوری دی گئی۔ اس کا خاکہ ایک عشرہ قبل دیا گیا تھا، مگر ابھی اس کا قیام باقی تھا۔ بتایا گیا کہ اسلامو فوبیا کے خلاف یہ ایک مؤثر فورم کا کام کرے گا اور مسلم دنیا کےلیے بیانیہ وضع کرنے کا بھی کام کرے گا۔
ایک ایسے عہد میں جب تاثرات کی جنگ سفارتی میدانوں سے پہلے ڈیجیٹل دنیا میں لڑی جاتی ہے، مسلم دنیا کے لیے اپنی کہانی خود سنانا — بغیر مسخ، تعصب یا بیرونی مفروضات کے — نہ صرف ثقافتی ضرورت ہے بلکہ ایک سیاسی ہتھیار بھی ہے۔فورم کے تحت تربیتی پروگراموں کا آغاز، کردار کشی پر فوری ردعمل کے نظام، اور عوامی نشریاتی اداروں و میڈیا ایجنسیوں کے درمیان ہم آہنگی کا فروغ متوقع ہے۔ ایسے وقت میں جب ایک وائرل کلپ یا جھوٹی خبر بین الاقوامی پالیسی کو کمزور کرسکتی ہے یا نفرت انگیزی کو ہوا دے سکتی ہے، تو یہ پہل علامتی نہیں بلکہ ایک تزویراتی ضرورت بن چکی ہے۔
اسلاموفوبیا سے نمٹنے کی حکمت عملی کے طور پر سفارش کی گئی کہ اشتعال انگیز تقاریر کو قابلِ سزا جرم بنانا اور مذہبی تعصب کے خلاف تعلیمی إصلاحات کرنا اور اقوام متحدہ کی شراکت سے ایسا عالمی نظام تشکیل دینا، جو مذہبی امتیاز کی تفتیش اور نگرانی کرکے اس پر فوری کارروائی کرے۔ جس بھی ملک سے کوئی شہری اس ادارہ کے پاس مذہبی امتیاز کی شکایت کرے، تو اس کا فوری ازالہ کیا جائے۔
اگر یہ اقدامات عملی شکل اختیار کر لیں تو یہ بین الاقوامی قانون میں مذہبی رواداری سے متعلق اسلامی دنیا کا پہلا بامعنی کردار ہو گا۔ عشروں سے مسلم ممالک تعصب اور نفرت کی نشاندہی کرتے رہے ہیں، اب وہ ان کا تدارک پیش کر رہے ہیں، یہ — ایک ایسی پیش رفت ہے جسے مغربی ممالک نظرانداز نہیں کر سکیں گے۔
اعلامیہ میں جہاں برما کے روہنگیا مسلمانوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، وہاں اس میں چین کے شین جیانگ یا چینی ترکستان کے اویغور آبادی کا تذکرہ نہیں تھا۔ چونکہ یہ اجلاس ہی استنبول میں منعقد ہورہا تھا، جہاں جلاوطن ایغور آبادی اچھی خاصی ہے، تو ان کا ذکر نہ کرنا نوٹ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ پچھلے اعلامیوں میں جب ایغور آبادی کا تذکرہ ہوتا تھا تو چین اس پر ناراض ہوتا تھا۔
چند برس قبل چین نے اس کا توڑ یہ نکالا کہ جدہ میں او آئی سی سیکرٹریٹ کےلیے ایک خصوصی سفیر کا تقرر کیا۔ جس کی وجہ سے اس کو اسلامی تنظیم کے اندر رسائی حاصل ہوگئی اور اس نے تنظیم کو پیش کش کی کہ وہ ہر سال مسلم ممالک کے وفد کو شین جیانگ کا دورہ کرنے کی اجازت دیں گے اور اگر وہاں عوام کی فلاح و بہبود کےلیے ان کو کوئی سفارش کرنی ہو، تو براہِ راست اسلامی تنظیم میں متعین چینی سفیر کو کیا کریں۔ اس کے بعد سے اعلامیہ میں ایغور آبادی کا ذکر آنا بند ہوگیا۔
اسی کانفرنس کے دوران او آئی سی سیکرٹریٹ نے چین کی وزارتِ تعلیم کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ جس کا مقصد وظائف، تعلیمی تبادلے اور مشترکہ تحقیق کے ذریعے انسانی وسائل کی ترقی ہے۔ جہاں او آئی سی عشروں سے مغربی اداروں سے منسلک رہی ہے، وہاں یہ شراکت ایک نئی جہت کی طرف اشارہ ہے۔ یوں — ترقی کے ایسے ماڈلز تیار کئے جائیں گے جو مغربی امداد کی شرائط سے آزاد ہوں گے۔ او آئی سی ممالک کے لیے یہ ایک قیمتی موقع ہے کہ وہ اپنی نوجوان نسل کو تعلیم، سائنس اور تحقیق کے میدان میں مغربی انحصار سے باہر نکلنے کے راستے فراہم کرے۔ چینی سفیر چانگ ہوا نے اس معاہدے کو مسلم دُنیا کے ساتھ تعلقات میں ’اہم سنگِ میل‘ قرار دیا اور تعلیم، سائنس و ٹکنالوجی، اور دیگر مشترکہ شعبوں میں مزید تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔
مسلم دنیا میں اعلیٰ تعلیم، سائنسی تحقیق، علمی تبادلہ اور ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک اسٹرے ٹیجک فریم ورک قائم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔جس میں بیس سے زائد جمہوریہ ترکیہ کے اعلیٰ تعلیمی ادارے شامل ہوںگے۔ اس کے ذریعے مشترکہ تحقیق، تربیتی پروگرام، اور رکن ممالک کی جامعات کے درمیان نیٹ ورکنگ کو تقویت ملے گی۔
اسی طرح او آئی سی مرکز برائے پولیس تعاون کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ جس میں ابتدا میں ترکیہ ، قطر، موریتانیا، گنی بساؤ، گیمبیا اور لیبیا وغیرہ شامل ہوں گے۔ یہ مرکز ایک رضاکارانہ ماہر ادارے کے طور پر تربیت، انٹیلی جنس شیئرنگ اور سرحد پار تعاون کو فروغ دے گا۔ دہشت گردی، سائبر جرائم اور انتہا پسندی جیسے چیلنجوں کے لیے مشترکہ ردعمل کی ضرورت ہے۔ اس مرکز کو وسعت دی جائے تو مسلم ممالک مغربی سیکیورٹی سانچوں اور ٹکنالوجی پر انحصار کم کر سکتے ہیں۔
صدر ایردوان نے افتتاحی خطاب میں کہا کہ ’’مسلم دنیا کو صرف ردعمل دینے والا نہیں، بلکہ راہ نمائی فراہم کرنے کا کردار ادا کرنا ہو گا۔ اس قیادت کا اندازہ تقریروں یا پریس ریلیز سے نہیں، بلکہ اُن اداروں، مراکز اور معاہدوں کے عملی اطلاق سے ہو گا جن کا اعلان کیا جائے گا‘‘۔
استنبول کا یہ اجلاس ردعمل پر مبنی نہیں بلکہ بھرپور اقدامات کی طرف گامزن ہونے کی نوید سناتا ہے۔ تاہم، اعلامیے کافی نہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی بین الحکومتی تنظیم اپنی آبادیاتی قوت کو ادارہ جاتی طاقت میں تبدیل کرے۔
ایران پر اسرائیل کے حملے کے حوالے سے وزرائے خارجہ نے ایک کھلے مینڈیٹ والے رابطہ گروپ کے قیام پر اتفاق کیا، جو دنیا کی بڑی طاقتوں سے رابطہ قائم کر کے کشیدگی میں کمی، اور اسرائیلی جارحیت کے احتساب کے لیے اقدامات کرے گا۔ وزرائے خارجہ نے ان کوششوں کی مذمت کی جو اسرائیلی حکام کی جانب سے القدس الشریف کی تہذیبی شناخت کو مسخ کرنے اور مسجد اقصیٰ کی قانونی و تاریخی حیثیت بدلنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔اعلامیے میں اردن کی حکومت کی کوششوں کو سراہا گیا، جو یروشلم میں اسلامی و مسیحی مقدس مقامات کی متولی ہے۔ بیت المال القدس ایجنسی اور القدس کمیٹی کے کردار کی بھی تعریف کی گئی۔ او آئی سی نے یونیسکو کی ان قراردادوں کا خیرمقدم کیا جن میں مسجد اقصیٰ کو اسلامی عبادت گاہ قرار دیا گیا اور اردن کی انتظامی بالادستی کو تسلیم کیا گیا‘‘۔
ایردوان نے کہا کہ ’’اسلامی تنظیم کے رکن ممالک کو صرف اپنے ہی مسائل کا حل نہیں نکالنا، بلکہ پوری دنیا کے مظلوموں کی آواز بھی بننا ہے۔ مسلم اقلیتیں، او آئی سی اور باقی دنیا کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہیں‘‘۔ ان کا اشارہ مغربی اور دیگر ممالک میں مسلم اقلیت کی طرف تھا، جو ایک پُل کا کام کرسکتے ہیں اور ان ممالک میں تنظیم کےلیے ایک اثاثہ ہیں۔ ان خدمات کے بدلے میں ان کے مفادات کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔
انھوں نے فلسطینی دھڑوں کے مابین اختلافات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ’’یہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا فلسطین کی حمایت میں متحد ہے مگر ہمارے بھائی آپس میں تقسیم کا شکار ہیں۔استنبول سے لے کر القدس تک، ترکوں سے لے کر کردوں تک، سنیوں سے لے کر شیعوں تک — ہمارا قبلہ ایک ہے، تو ہمارا مقصد اور مقدر بھی مشترک ہے‘‘۔
او آئی سی نے اقوامِ متحدہ میں مشترکہ سفارتی اقدام شروع کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا مقصد اسرائیل کے خفیہ جوہری پروگرا م کو دنیا کے سامنے کھولنے اور اس کو جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ایک بند کمرہ اجلاس میں کیا گیا، جو ایران کی درخواست پر منعقد ہوا۔
ایردوان نے مغربی طاقتوں پر دوہرے معیار برتنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا: ’’ایران جیسے این پی ٹی پر دستخط کنندہ ممالک پر دباؤ ڈالنے والے یہ کیسے نظرانداز کر سکتے ہیں کہ اسرائیل نہ صرف اس معاہدے سے باہر ہے، بلکہ معائنے کو بھی رد کرتا ہے؟ ‘‘
لگتا ہے کہ استنبول میں منعقدہ یہ اجلاس صرف تقاریر یا قراردادوں تک محدود نہیں رہا۔ اس نے اُمت ِ مسلمہ کے لیے ایک نیا راستہ متعین کیا ہے، جو جوہری توازن کی بحالی، مظلوموں کے دفاع، اور عالمی انصاف کے قیام پر مبنی ہے۔ آنے والے دن اس بات کا امتحان ہوں گے کہ اسلامی تعاون تنظیم صرف آواز بلند کرے گی یا اپنے کسی اعلان پرعمل بھی کرے گی؟
کشمیر کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے، مگر بعض چہرے تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جاتے ہیں۔ برہان مظفر وانی شہید انھی چہروں میں سے ایک ہے، جس نے کم عمری میں برہمنی تسلط کے خلاف بندوق اٹھا کر قابض انڈین فوجیوں کو چیلنج کیا، اور اپنی شہادت سے تحریکِ آزادی کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا۔ اس جدوجہد کا فکری محور وہی تھا، جو قائدِ حریت سیّد علی گیلانی پوری زندگی دہراتے رہے:’ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے!‘
برہان وانی ۱۹۹۴ء میں ڈاڈہ سرہ ترال کے ایک علمی اور باوقار گھرانے میں پیدا ہوا۔ ان کے والد مظفراحمد وانی اسکول پرنسپل، والدہ پوسٹ گریجویٹ، اور دادا ریاستی محکمۂ منصوبہ بندی میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر فائض رہے۔ پورے علاقے میں اس خاندان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مگر غلامی کے سائے میں باعزّت خاندان بھی محفوظ نہ رہے۔۹۰ کے عشرے میں انڈین فوجیوں کے ہاتھوں بُرہان وانی کی نظروں کے سامنے نعیم اور عادل جیسے قریبی رشتہ دار بھی شہید کر دیے گئے۔ گھر پر بار بار چھاپے، بے جا تلاشی، اور توہین آمیز رویہ ان کے لیے روز کا معمول بن چکا تھا۔
انھی سخت اور پرآشوب حالات میں برہان وانی نے پرورش پائی۔ وہ اسکول جاتا، مگر چاروں طرف انڈین فوجیوں اور ریاستی پولیس فورس کے مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ ۲۰۱۰ء میں جب اس نے اپنے بھائی کو بھارتی اہلکاروں کے ہاتھوں لہولہان اور بے ہوش ہوتے دیکھا، تو اس کے اندر حُریت کی اُمنگ بھڑک اٹھی۔ غلامی کے خلاف جذبات نے فیصلہ کن شکل اختیار کرلی، اور وہ مجاہدینِ آزادی کی صفوں میں شامل ہو گیا۔’شیر کی ایک دن کی زندگی‘ کا فلسفہ اس کے لیے فقط قول نہیں، زندگی کا نصب العین بن گیا۔
محض ۱۵ برس کی عمر میں اس نے ’حزب المجاہدین‘ میں شمولیت اختیار کی، جس کی قیادت سیّدصلاح الدین کر رہے تھے۔ برہان وانی کی وابستگی صرف عسکری نہ تھی، بلکہ فکری طور پر وہ سیّد علی گیلانیؒ کو اپنا امام مان چکا تھا۔ وہ امام گیلانی کی ’ایمانی استقامت‘ اور صلاح الدین کی ’عسکری قیادت‘ کا عملی امتزاج بن گیا۔
برہان وانی نے بندوق کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو مزاحمت کا محاذ بنایا۔ اس کی ویڈیوز، تصاویر، اور بیانات نے انڈین پراپیگنڈے کو شکست دی، اور حُریت پسندی کی ایک نئی علامت تراشی___ —ایمان، جوانی، سادگی، اور نظریاتی پیکر۔ اس نے فرضی نام یا خفیہ شناخت کے بجائے اپنا اصل نام اپنایا۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پولیس اہلکاروں سے ہتھیار چھین کر، انھی ہتھیاروں کو قابض فورسز کے خلاف استعمال کرنے کا ہنر سیکھا۔
سوشل میڈیا ٹیم کی تنظیم سازی، حکمتِ عملی اور ابلاغ میں اس کی قائدانہ صلاحیتیں نمایاں ہوئیں، اور جلد ہی حزب المجاہدین کی قیادت اس کے سپرد کردی گئی۔ اس نے نوجوانوں میں نئی روح پھونکی اور حزب کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا۔ درجنوں نہیں، سیکڑوں نوجوان اس کی دعوت پر حزب میں شامل ہوئے، اور جو لوگ عسکریت کے خاتمے کی باتیں کر رہے تھے، وہ خاموش ہوگئے۔ نائب امیر حزب، سیف اللہ خالد کے مطابق، شہادت سے بیس دن قبل برہان وانی نے یہ پیغام دیا تھا: ’’کشمیری قوم نہ جھکے گی، نہ بکے گی۔ ان شاء اللہ ضرور آزادی حاصل کرکے رہے گی‘‘۔اس نے کہا تھا کہ ’’جو بھی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، ان سے حق ادا کرنے کی کوشش کریں‘‘،اور اس نے اپنی شہادت کی دعا بھی انھی الفاظ میں کی تھی۔
۸جولائی ۲۰۱۶ء کو جب برہان مظفر وانی کی شہادت کی خبر پھیلی، تو وادی میں زلزلہ آ گیا۔ بھارت نے اُس کی مقبولیت کو ختم کرنے اور تحریکِ آزادی کو دبانے کے لیے ظلم کی انتہا کر دی۔
۲۰۰ سے زائد شہادتیں، ۱۵ ہزار سے زیادہ زخمی، اور ۲۰ ہزار سے زائد گرفتاریاں کیں، —جن میں طالب علم، ائمہ، اور سیاسی کارکن شامل تھے۔ مظاہرین کو کچلنے کے لیے پیلٹ گنز کو استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں ۱۵۰۰ سے زائد نوجوان مستقل طور پر بینائی سے محروم ہوگئے۔ اُسی روز امام سیّد علی گیلانیؒ نے فرمایا:’’برہان شہید ایک نظریہ ہے، اور نظریات کو گولی سے نہیں مارا جاسکتا‘‘۔واقعی، برہان وانی کی شہادت کے بعد ہزاروں نوجوانوں نے تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ سید صلاح الدین نے کہا تھا:’’بھارت نے ایک برہان کو شہید کیا ہے، لیکن ہزاروں برہان پیدا ہو گئے ہیں‘‘۔یہ بات محض دعویٰ نہ رہی؛ سبزار بٹؒ، ریاض نائیکو ؒ، ڈاکٹر منان وانیؒ، اور پروفیسر رفیعؒ بٹ سبھی کسی نہ کسی شکل میں برہان وانی شہید سے متاثر تھے۔
۵؍ اگست ۲۰۱۹ء کو بھارتی حکومت نے آرٹیکل ۳۷۰ اور ۳۵-اے کی منسوخی کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر کا آئینی تشخص ختم کر دیا۔ لاکھوں فوجی پہلے ہی موجود تھے، مزید ۸۰ہزار سے زائد تعینات کر دیے گئے۔ ہزاروں رہنما، کارکن، صحافی گرفتار یا نظربند ہوئے۔ سیّد علی گیلانیؒ کو نظربند رکھا گیا، حتیٰ کہ وہ اسی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔
UAPA جیسے قوانین کے ذریعے صحافت کو جکڑا گیا، دفاتر پر چھاپے، صحافیوں پر مقدمات، اخبارات کی بندش، اور ڈومیسائل قانون کے ذریعے آبادیاتی تبدیلی کی مذموم کوشش کی گئی۔
اب سوال یہ ہے:کیا برہان وانی شہید صرف ماضی کی ایک یاد ہے؟کیا کشمیری عوام نے ظلم کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں؟جواب واضح ہے: نہیں۔بھارت لاکھ جبر کرے، برہان وانی شہید آج بھی کشمیری قوم کے اجتماعی شعور میں زندہ ہے۔تحریکِ آزادی آج بھی جاری ہے۔گرچہ عسکری مزاحمت کا انداز بدل چکا ہے، مگر جذبہ، ایقان اور مزاحمتی روح پہلے سے زیادہ توانا ہے۔ برہان وانی شہید اُس تحریک کا مظہر تھا جس کی فکری بنیادیں شہید علی گیلانیؒ نے رکھی تھیں، اور جو آج بھی ہر ظلم کے خلاف آواز بن کر ابھرتی ہے۔برہان وانی شہید فقط ایک مزاحمت کار نہ تھا، بلکہ وہ ہرکشمیری کے خواب کا استعارہ بن چکا ہے۔ایک ایسا خواب جو نسل در نسل دلوں میں جاگتا ہے، بستی بستی گونجتا ہے۔
برہان وانی شہید چلا گیا، مگر اس کی شہادت تحریکِ مزاحمت کا ایسا باب بن گئی ہے جو ہرکشمیری نوجوان کے دل کی آواز ہے، ہر ماں کی دعا میں شامل ہے، اور ہر ظلم کے جواب میں نعرہ بن کر ابھرتا ہے: ’’برہان! تیرا خون رنگ لائے گا!‘‘
مملکت ِ خدادادِ پاکستان میں سیاسی ، معاشی ، سماجی ، تہذیبی ونظریاتی ، قومی سلامتی اور ملت اسلامیہ کو درپیش مسلسل بڑھتے بحرانوںکے حل کے لیے سرجوڑ کر بیٹھنے اورتبادلۂ خیال کی ضرورت ہے، اور بحرانوں میں گھرے پاکستان کو ان بحرانوں سے نجات دلانے کے لیے سیاسی وقومی قیادت کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
ملک کا قومی بجٹ ۲۶-۲۰۲۵ء قومی اُمنگوں کے برعکس ہے جس نے واضح کردیاہے کہ حکومت معاشی محاذ پر بھی سخت ناکامی سے دوچار ہے۔ ۲۵کروڑ عوام آئی ایم ایف کی غلامی پرمجبور کردیئے گئے ہیں۔۴۵فی صد عوام خطِ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ زراعت ، صنعت اور تنخواہ دار طبقہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ یہ معاملہ زیادہ تکلیف دہ ہے کہ حکمرانوں سمیت ریاستی ادارے اور اشرافیہ کرپشن،مفت خوری اور اپنی عیاشیاں ترک کرنے کو تیار نہیںہیں۔ قرضوں کی لعنت ،کرپشن اور سودی قرضوں کا بوجھ قومی سلامتی کے لیے زہرِ قاتل ہے۔ بلاشبہ دفاع کے لیے اخراجات ناگزیراور اہم ہیں ، لیکن قرضوں کی ادائیگی ، اشرافیہ کی عیاشیاں ،جاگیر داروں اور بڑ ے لینڈ لارڈ ز کو ٹیکس نیٹ سے باہر رکھنا، نیز آئی پی پیز معاہدوں میں تبدیلی اور بنکوں کی شرح سود میں کمی کا ریلیف عوام کو نہ دینا خیانت ہے۔ پھر زیادتی یہ کہ صارفین کے لیے سستی بجلی کے لیے سولر انرجی پر بھی ناروا ٹیکسوں کا نفاذ ہے۔ کرپشن کا بڑھتا ہوا ناسور حالات کو انتہائی غیر متوازن اور تکلیف دہ بنا رہا ہے۔ معاشی بحران کے خاتمے کے لیے حکمرانوں کی معاشی ٹیم میں نہ صلاحیت ہے اور نہ اہلیت موجود ہے۔ سیاسی بحران کے خاتمے کی طرح معاشی بحران کے خاتمے کے لیے بھی قومی سطح پر مذاکرات اور ’میثاق معیشت‘ ناگزیر ہے ۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو سنجیدگی سے سیاسی و اقتصادی بحرانوں کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
’مائنز اینڈ منرلز ایکٹ‘ کے مسودات وفاق اور فوجی ادارے کی طرف سے منظوری کے لیے صوبوں کو بھیجنا آئین اورصوبائی خود مختاری کاگلا گھوٹنے کے مترادف ہے۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان بڑھتا الجھاؤ قومی وحدت بالخصوص وفاق پاکستان کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات معمول پرآنے سے ہی امن وامان کی صورتِ حال میں بہتری ممکن ہے۔
ہم چند بنیادی اُمور پر توجہ مبذول اور عمل درآمد کے لیے نشان دہی کر رہے ہیں:
قومی،جمہوری وسیاسی جماعتوں سے رابطے اور اچھے تعلقاتِ کار سیاسی ماحول اورفضا کو بہتر بنانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ سیاسی قوتوں کا آپس میں میل جول رابطہ اور تعلقاتِ کار وقت کا تقاضا ہے۔ ہر جماعت کااپنی اپنی سیاسی حکمت عملی کے ساتھ سیاسی قیادت اور جماعتوں کے ساتھ قومی سطح پر رابطہ نہایت کارآمد اور مفید ہے۔
مجوزہ قومی ایجنڈا: سیاسی بحرانوں سے نجات اور خوش حال پاکستان کے لیے درج ذیل بارہ نکاتی ایجنڈا بنیاد بن سکتا ہے:
قومی زندگی کے ان مسائل کے حل کے لیے عوامی جمہوری مزاحمت کی لہر جتنی تیز ہوگی، مسائل کے حل کی طرف قدم اتنی تیزی سے بڑھیں گے۔ قومی وعالمی ایشوز پر قومی اتفاق رائے کے لیے مثبت قومی کردار، عوام کے اتحاد اور تحرک کے لیے کش مکش، محنت اور جدوجہد کے ذریعے ہی پاکستان میں آئین کی فرمانروائی عوام کی اُمنگوں اور حقوق کی ترجمان ہو گی۔
جب ایسٹ انڈیا کمپنی نےاختیارات اپنے ہاتھ میں لیے،تو اس نے اہلِ ہند کے خلاف برطانیہ میں ، یہ بے بنیاد پروپیگنڈا کیا کہ اہلِ ہند اَن پڑھ، بے تہذیب اور وحشی ہیں، لہٰذا انھیں تعلیم دینے اور مہذب بنانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ تاجِ برطانیہ نے اہلِ ہند کی تعلیم کے لیے ۱۸۱۳ء میں، کمپنی کے چارٹر میں ، ایک لاکھ امداد کی مد شامل کی، اور پس پردہ تعلیمی نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کا منصوبہ بنایا۔
ابتدائی دور میں تعلیم حسبِ سابق ، فارسی و عربی میں دی جاتی تھی۔مگر ۱۸۳۵ء میں یہاں رہنے والوں کو اپنے علمی ورثے سے محروم کرنے اور ماضی کی تاریخ سے اس کا رشتہ منقطع کرنے کےلیے، انگریزی زبان میں تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا، اور ملازمت کا حصول انگریزی زبان کے ساتھ مشروط کر دیا گیا۔یہی وہ آرزو اور خواہش تھی جو چارلس گرانٹ نے برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کی تھی کہ پارلیمنٹ ،حکومت اہلِ ہند کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کرے، انھیں مغربی علوم، سائنس و ٹکنالوجی کے علاوہ عیسائیت کی تعلیم دے، اور ذریعۂ تعلیم انگریزی کو بناتے ہوئے انگریزی زبان و ادب کو نصاب میں شامل کرے۔ اس وقت علما انگریزی سیکھنے کے مخالف نہ تھے، اور بہت سے نامی گرامی علمانے انگریزی اور پرتگالی زبانیں سیکھی تھیں ۔۱؎ خودشاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے انگریزی سیکھنے کے جواز کا فتویٰ دیا تھا ۔۲؎
مسلمان جس چیز کے خلاف تھے، وہ عیسائی مدارس کے اندر مسیحیت کی تعلیم، ان کی تہذیب، لباس و اطوار اور بائیبل کی لازمی تدریس تھی، جب کہ پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ مسلمان تعلیم کے خلاف ہیں۔ ۱۸۴۰ء میں ایک اور حکم نافذ کیا گیا، جو مسلمانوں کے لیے ایک نئی اور عجیب چیز تھی، کہ پڑھانے کے عوض ہرطالب علم سے فیس وصول کی جائے ۔۳؎ یعنی تعلیم کو پہلی دفعہ کمائی کا ذریعہ بنایا گیا۔
یہ وہ دور تھا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانب سے ٹیکسوں کی بھرمار تھی۔ اہلِ ہند عموماً، اور مسلمان بالخصوص اِن کا شکار تھے۔ ایسی حالت میں، جب کہ لوگ پیٹ بھرنے کی فکر میں تھے، ان پر تعلیم کی مد میں مزید فیس عائد کرنے کا مطلب، انھیں تعلیم سے محروم کرنا تھا۔ اس حکم نامے سے ہندوؤں سے زیادہ، مسلمان متاثر ہوئے، اور یہ چیز انھیں تعلیم کے میدان میں پیچھے دھکیلنے کا سبب بنی۔ اس حقیقت کا اعتراف اس وقت کےسیکریٹری وزارتِ داخلہ ہیلی (۱۸۶۰ء ) نےبھی کیا ہے: ’’کیا یہ حیرت کا مقام ہے کہ مسلمان ایک ایسے نظام سے کنارہ کش رہے، جو پورے طور پر ان کے مفاد کے منافی تھا، اور ان کی تمام مجلسی روایات کے خلاف تھا۔ تعلیم یافتہ مسلمان دیکھ رہا ہے کہ اسے اختیارات کے حصے اور حکومتی مراعات سے محروم رکھا گیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی کے تمام فوائد ہندؤوں کے حوالے کر دیئے گئے ہیں‘‘ ۔۴؎
مسلمان علما نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے ، اور ہندوؤں کو ترجیح دی جارہی ہے، تو انھوں نے خود جدید مدارس قائم کرنے کی طرف توجہ دی۔مگر انھیں اپنی مرضی سے جدید مدارس قائم کرنے کی اجازت نہ تھی۔مفتی ولایت اللہ نے اپنے خرچ پر فتح گڑھ میں سکول کی ایک خوب صورت عمارت بنوائی ، اور اس کے لیے کچھ سرمایہ وقف کیا۔ پھر کلکتہ کی مجلسِ تعلیمات سے اس کی منظوری لینے کے لیے درخواست دے دی، جو ٹال مٹول کے بعد بالآخر سرد خانے کی نذر ہوئی ۔۵؎
مسلمانوں کے ’وقف‘ سے چلنے والے بہت سارے تعلیمی اداروں کی پہلے گرانٹ بند کر دی گئی، پھر اگلے مرحلے میں انھیں اپنے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ اس پر مزید ظلم یہ کیا گیا کہ اس وقف املاک کی رقم سے انگریزی کالج بنائے گئے، اور پھر زیادتی یہ بھی کی گئی کہ ان کالجوں میں ہندو طلبہ کو داخلے دیے گئے، اور کسی مسلمان کو ان میں داخل نہ ہونے دیا گیا۔ اسی فتح پور کے کالج میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی برتاؤ پر جب مسلمانوں نے بھر پور احتجاج کیا ، تو صرف ۳۰طلبہ کو داخلہ دیا گیا، جب کہ اس کالج میں ہندو طلبہ کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ تھی ۔۶؎
یہ تمام حربے اہلِ ہند کو ، بالخصوص مسلمانوں کو تعلیم سے دُور رکھنے کے لیے استعمال کیے جارہے تھے۔اس کی وجہ کمپنی کے ڈائریکٹر جیکسن نے واشگاف الفاظ میں برطانوی پارلیمنٹ میں بیان کی تھی:’’ ہم نے امریکا میں اسکول اور کالج کھولے ، امریکا کو کھو دیا۔ اب ہم ہندوستان میں اس غلطی کا اعادہ نہیں کریں گے‘‘ ۔۷؎
اس دور میں اردو ، ہندوستان کی قومی زبان کی حیثیت اختیار کر چکی تھی اور ملک کے طول و عرض میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔مگر جب پرتگیزی گورے آئے تو انھوں نے پرتگالی میں تعلیم دینی شروع کی، اور جب انگریز گوروں نے قبضہ جمایا تو انھوں نے انگریزی کو بطورِ ذریعۂ تعلیم لازمی قرار دیتے ہوئے اسے نافذ کیا۔مگر ساتھ ساتھ سامراج نے اپنی انتظامی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے علاقائی زبانوں کو بھی تعلیم میں شامل کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصےبعد، ملک میں ،ایک ہندوستانی کے بجائے مرہٹی، بنگالی، سندھی اور کوکنی وغیرہ قومیتیں ابھرنے لگیں۔ اردو جو کہ قومی زبان تھی، اس کے مقابلے میں دیوناگری زبان کو زندہ کرنے اور رائج کرنےکی ناکام کوششیں کی گئیں ۔۸؎
تعلیم کے میدان میں ایک اور بڑا انقلابی قدم یہ اٹھایا گیا، کہ تعلیم کی ذمہ داری عیسائی مذہبی پیشواؤں کے سپرد کی گئی۔ عیسائی مشنریوں نے ملک کے طول و عرض میں تعلیمی ادارے کھولے، جہاں عیسائیت کی لازمی تعلیم دی جاتی تھی۔ساتھ ہی، انھوں نے دیگر مذاہب، بالخصوص اسلام پر کھل کر اعتراضات کرنے شروع کیے، مناظرہ بازی کو ترویج دی گئی، اور نصابات کے ذریعے ہندؤوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا گیا۔ حالانکہ ہندو اور مسلمان صدیوں سے یہاں اکٹھے رہ رہے تھے اور عمومی طور پر ان کے درمیان اس طرح کے مذہبی جھگڑے پیدا نہ ہوئے تھے۔ ہندستانی امور کے وزیر، جارج سیل فرانسس ہملین، نے ۲۶ مارچ ۱۸۸۸ء کو لکھا تھا: ’’ہمیں نصابی کتب اس طرح تیار کرنی چاہئیں کہ مختلف [نسلی و لسانی و مذہبی] فرقوں کے درمیان اختلافات کو تقویت حاصل ہو‘‘ ۔۹؎ اس سے کوئی ڈیڑھ ماہ قبل، کراس نامی ایک اور انگریز نے گورنر جنرل ڈفرن کو لکھا: ’’مذہبی اختلافات ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔مجھے امید ہے کہ ہندستانی تعلیم و تدریس سے متعلق کمیٹی، اس بات کا خیال رکھے گی‘‘۔۱۰؎
ہندستان کی نئی نسل کو جسمانی طور سے کمزور، مزاج کے لحاظ سے کند اور عقل کے لحاظ مفلوج کرنے کے لیے ، پورے منصوبے کے تحت جنوبی امریکا سے لال مرچ، تمباکو اور افیون کو لاکر یہاں کاشت کیا گیا۔لارڈ میکالے نے اپنے ایک بیان میں اسے کھل کر یوں بیان کیا: ’’ہم افیون کے کاشت کی منظوری پوری قوم کو افیون کا عادی بنانے کے لیے نہیں دیں گے،بلکہ اس مذموم مقصد کے لیے دیں گے کہ وہ ہمارے غلبے کو قبول کریں‘‘۔۱۱؎ ڈپٹی نذیر احمد کے بقول:’’ہندوستان میں بچوں کو افیون دینے کا ایسا رواج ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان بچہ اس سے محفوظ ہو‘‘۔۱۲؎
یہی وہ نشہ اور تعلیمی نظام ہے، جس کے بارے میں میکالے کے بہنوئی چارلس ٹریویلین نے ۱۸۳۸ء میں اپنی کتاب میں لکھا تھا: ’’غلام ہندوستان کے پاس آزادی حاصل کرنےکے دو راستے ہیں: ایک انقلاب کا اور دوسرا اصلاح کا۔انقلاب کی صورت میں ایک مہینہ میں ’مرہٹہ‘ یا ’اسلامی حکومت‘ قائم کی جا سکتی ہے۔لیکن اصلاح کے ذریعے ہندوستان کو آزادی کے لیے ایک صدی درکار ہوگی‘‘۔۱۳؎ ان کا یہ تجزیہ وقت نے درست ثابت کیا، کہ اہلِ ہند نے آزادی کے لیے انقلاب کے بجائے اصلاح کا راستہ اختیار کیا تو ۱۸۳۸ء سے ۱۹۴۷ء تک انھیں ایک صدی سے زیادہ عرصہ لگا۔
دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں یورپ و امریکا طاقت کے ذریعے ملکوں پر قبضہ کرنے سے بہت بدنام ہوئے ، تو اس سامراج نے ان ملکوں کو غلام بنائے رکھنے کے لیے بالواسطہ طریقہ اختیار کیا۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں (MNCs) نے اقوام متحدہ (یو این او) بنائی۔ اقوامِ متحدہ کی چھتری کے نیچے ورلڈ بنک، ایشین بنک اور ’انٹرنیشنل مانٹیری فنڈ‘ (آئی ایم ایف)جیسے ادارے بنائے گئے۔ اور پھر ان ممالک میں این جی اوز بناکر،امداد کے نام پر، اپنی شرائط کے تحت، سودی قرضے دے کر، ملکوں کے نظام کو اپنے کنٹرول میں لیا۔
این جی اوز کو ۱۹۸۰ء کے عشرے سے کھل کر کھیلنے کا موقع ملا اور اکیسویں صدی کے آغاز میں پاکستان پر ڈکٹیٹرجنرل پرویز مشرف نے بین الاقوامی دبائو کے تابع آکر تعلیمی پالیسی کے خدوخال وضع کیے۔یہ پالیسی ۲۰۰۶ء میں تیار کرکے تعلیمی میدان میں تبدیلی لانے کے لیے نافذ کی گئی۔ یہ تعلیمی پالیسی بھی وزارتِ تعلیم کے نصابات ونگ میں تیار نہیں ہوئی، بلکہ یہ اسلام آباد میں،’ پیس‘ نامی امریکی این جی اوکے ادارہ میں بیٹھ کر بنائی گئی۔۱۴؎ درحقیقت اس تعلیمی پالیسی کے نتیجے میں ہی این جی اوز کی سرگرمیوں میں بڑی وسعت آئی۔
ہم یہاں ڈیرہ اسماعیل خان کی مثال دیتے ہیں، جہاں کرپشن کی ثابت شدہ انکوائریوں میں ایک فرد کو ، جسے یونی ورسٹی سینڈیکیٹ نےا س کے انتظامی عہدے کے لیے نا اہل قرار دیا تھا، اسے بورڈ میں کنٹرولر لگا دیا گیا۔ شکایات پر اسے وہاں سے ہٹادیا گیا، مگر ساتھ ہی اسے ایک یونی ورسٹی میں وائس چانسلر بنا دیا گیا۔ یونی ورسٹی کے ایک ایڈیشنل کنٹرولر کو، جس پر کئی افراد کو جعلی ڈگریاں دینے کا الزام عدالت سے ثابت ہو چکا تھا، اسے وہاں سے اٹھا کر یونی ورسٹی کا کُل وقتی کنٹرولر بنادیا گیا۔ ملک بھر میں وائس چانسلرز کو میرٹ کے بجائے چیف منسٹرز کی خواہش پر لگا یا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ آئے روز مختلف سکینڈلز کی صورت میں، اخبارات کی زینت بنتا رہتا ہے۔یوں تعلیم کو سیاستدانوں اور کرپٹ مافیا کا کھلونا بنا دیا گیا ہے۔
اس وقت سیاسی ، معاشرتی اور تعلیمی میدان میں انہی خطوط پر این جی اوز کام کر رہی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ موجودہ نظریاتی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکا جائے، اداروں اور ملک کو توڑا جائے اور پھر نئے سرے سے ایک ملک وجود میں آئے جس کا نام ’اکھنڈ بھارت‘ ہو۔اس توڑ پھوڑ اور ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے نقشے بنا کر بچوں کی کتابوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں مخصوص نظریات کی حامل این جی اوز نے ریاست کے اندر ایک اور ریاست قائم کر رکھی ہے۔ اربابِ اختیار مال کے مزے لوٹ رہے ہیں تو این جی اوز نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت، اخلاق و تہذیب کی بربادی پراپنے آقاؤں سے داد وصول کر رہی ہیں۔
۱- سب سے بنیادی اور پہلا کام تعلیم کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔تعلیمی نظام کو اسلامی خطوط پر تشکیل دیا جائے۔ تعلیم کو صنعت کے بجائے پھر سے عبادت اور فرض کا درجہ دیا جائے اوراسے ریاست کی ذمہ داری قرار دیا جائے۔
۲- پوری دنیا کی طرح تعلیم کو مرکز کے ماتحت کرنے کے لیے آئینی ترمیم لائی جائے اور صوبوں میں دھکیلنے سے واپسی کا راستہ اپنایا جائے۔
۳- ایک آزاد اور خود مختار تعلیمی کمیشن بنایا جائے، جوپبلک سیکٹر کی جامعات، کالجوں، ہائی اور پرائمری اسکولوں کے ماہرینِ تعلیم، اساتذہ اور طلبہ نمائندوں پر مشتمل ہو،جو نہ صرف خرابیوں کا جائزہ لے سکے، بلکہ اصلاحات تجویز کرتے ہوئے ان کو عملاً نافذ بھی کرسکے۔
۴- پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک ہی نصاب، قومی زبان ذریعۂ تدریس ہو، ایک ہی نظامِ امتحانات اور ایک ہی لباس ہو۔دونوں سیکٹرز یعنی پبلک و پرائیویٹ کوایک ہی قانون اور نظام کا پابند بنایا جائے، اورتعلیم میں تجارتی رجحان کا خاتمہ کیا جائے۔
۵- تعلیمی اداروں میں سیاسی و بیرونی مداخلت کو قانوناً ممنوع قرار دیا جائے اور اسے ممتا ز خود مختار ماہرین تعلیم پر مشتمل کمیشن کے ماتحت کیا جائے۔
۶- تعلیمی نظام اور اداروں میں غیر ملکی این جی اوز کی مداخلت پر پابندی لگائی جائے، اور اب تک تعلیم کے نام سے خرچ کیے جانے والے اربوں کے اخراجات کا آڈٹ کیا جائے۔ کرپشن میں ملوث اور تعلیم کی آڑ میں ملکی نظریات اور مفاد کے خلاف کام کرنے والی این جی اوز پر پابندی لگائی جائےاور ملوث ذمہ داراں کو قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے۔
۷- ملک کے اندر تعلیمی نجکاری کی پالیسی کو ختم کی جائے ۔
۱- ڈاکٹر معین الدین عقیل، مسلمان اور مغربی تعلیم، ص۵۳-۵۴
۲- فتاویٰ عزیزیہ، بحوالہ سید محمد سلیم،ص ۲۶
۳- سیّد محمد سلیم، مسلمان اور مغربی تعلیم، ص۲۰۶
۴- ایضاً، ص ۲۰۷
۵- عبداللہ یوسف علی، انگریزی عہد میں ہندوستان کے تمدن کی تاریخ، ص ۱۷۲
۶- ایضاً
۷- مسلمان اور مغربی تعلیم، ص۱۳۸
۸- سیّد مصطفیٰ علی بریلوی، مسلمانانِ سندھ کی تعلیم، آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس، کراچی، ۱۹۸۶ء، ص۶۵-۶۸
۹- سیّد عابد علی وجدی، تاریخِ ریاستِ بھوپال، مقدمہ ص۷
۱۰- ایضاً
۱۱- مسلمان اور مغربی تعلیم، ص ۷۰-۷۲
۱۲- ایضاً
۱۳- ناصر عباس نیر، تعلیمی زاویئے: نوآبادیاتی تعلیمی دور، ۲۴؍ اگست ۲۰۱۶ء
۱۴- تعلیمی پالیسی ۲۰۰۶ء، تعارف۔
سوال: جدید معاشرے کے حالات و اَطوار بہت بدل چکے ہیں۔ جرم اور سزا کا تصور بدل چکا ہے۔ ماضی کی ’اسلامی ریاست‘ میں اور موجودہ دور کی ’جدید ریاست‘ میں بڑا فرق رُونما ہوچکا ہے۔ سعودی عرب کے معاشرتی حالات اور شکاگو اور نیویارک جیسے بڑے بڑے شہروں کی معاشرتی کیفیت اور ساخت بالکل مختلف ہے۔ اس لیے [ماضی کے] ایک محدود شہری نظام کے لیے اگر اسلامی سزائیں مفید بھی تھیں، تو [آج] بڑے بڑے شہروں کے لیے یہ کس طرح کارآمد ہوسکتی ہیں، جب کہ ان میں جرائم کا رُونما ہونا ایک حد تک فطری بات ہے، اور ان میں سزائوں کا عملی نفاذ، کوئی آسان کام بھی نہیں؟
جواب: آپ کا خیال ہے کہ شکاگو اور نیویارک جیسے بڑے بڑے شہروں کی Social Life (معاشرتی زندگی) ہی ایسی ہے کہ ان کے اندر جرائم کا ہونا ایک فطری چیز ہے۔ اس لیے اس حالت کے خاتمے کے لیے ہاتھ کاٹنے جیسی سزائوں کا نفاذ ایک غیرترقی یافتہ بات ہے اور آپ کے خیال میں یہ عملاً ممکن بھی نہیں۔
لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے اور اگر صرف چوری پر ہاتھ کاٹنے کا قانون جاری کر دیا جائے تو نیویارک اور شکاگو جیسے شہروں، بلکہ پورے امریکا میں چوری کا ارتکاب کم ہوسکتا ہے۔ اس کا مکمل خاتمہ تو صرف اسی صورت میں ممکن ہے،جب کہ پورا سیاسی اور معاشرتی نظام اسلامی خطوط پر قائم کیا جائے، لیکن اسلامی سزائوں کے نتیجے میں اس میں کمی واقع ہوسکتی ہے… ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اسلام کی تجویز کردہ سزائیںمعاشرے سے جرائم کا مکمل انسداد کرسکتی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلام کا مکمل ضابطۂ حیات جاری ہو اور اسلامی تعزیرات نافذ ہوں۔ پھر ہم دُنیا کو بتائیں گے کہ ہمارے ہاں جرائم کس طرح کم ہو گئے ہیں اور اس طرح عملاً دُنیا پر یہ بات ثابت کردیں گے کہ اسلام کی بنیادوں پر ایک جدید ریاست چل سکتی ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے چل سکتی ہے ،اور اسلام کی بنیاد پر ایک ایسامعاشرہ وجود میں آتا ہے جو جرائم سے پاک اور امن و امان کا گہوارا ہوتا ہے۔
سوال: لیکن میرا خیال یہ ہے کہ روایتی اسلامی قانون کا یہ پہلو ایسا ہے کہ آج کا انسان اس کو قبول کرنے میں دِقّت محسو س کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان سزائوں کا تعلق اسلامی قانون سے ہے اور اس کو قبول کرنے میں مذہبی تعصب مانع ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید ذہن کے لیے کسی جرم پر ایک شخص کا ہاتھ کاٹ کر اسے ایک عضو سے محروم کر دینا ایک وحشیانہ فعل معلوم ہوتا ہے، اور شاید یہ اس جرم سے بھی سنگین نوعیت کی چیز ہے۔ اسی بناپر بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ریاست کی طرف سے کسی شخص کی جان لینے کا اقدام بہرحال ایک غیرمعمولی نوعیت رکھتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرونِ وسطیٰ کے ایک نظام کو خواہ وہ اپنی جگہ پر مفید ہی تھا، جدید دور میں رائج کرنا کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتا ہے۔
جواب: میرا خیال ہے کہ آپ کی موجودہ تہذیب کو، جسے آپ ’جدید تہذیب‘ کہتے ہیں، جتنی ہمدردی مجرم کے ساتھ ہے اتنی ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ نہیں جن پر جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، مثلاً ایک شخص کا بچہ کوئی اغوا کرکے لے جاتا ہے۔ اور پھر اس کو اطلاع دیتا ہے کہ ’’اتنے ملین ڈالر مجھے دے دو تو بچّہ تمھیں مل جائے گا ورنہ اسے قتل کردیا جائے گا‘‘ اور بعض اوقات وہ ایسا کربھی گزرتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کے آدمی کو پکڑ کر اگر کوئی سخت سزا دی جائے، مثلاً اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے یا اس کی گردن اُڑا دی جائے ،تو کیا یہ ایک وحشیانہ فعل ہوگا؟ یعنی آپ کے نزدیک والدین کو ان کے بچوں سے محروم کر دینا کوئی وحشیانہ حرکت نہیں۔ البتہ اس حرکت کے مرتکب کو اس کے جرم کی سزا دیناوحشیانہ اور ظالمانہ فعل ہے، جس کی کم از کم ریاست کو ذمہ داری نہیں لینی چاہیے۔ آپ کی ساری ہمدردی اس شخص کے ساتھ ہے، جس نے ایک مجرمانہ اور غیرانسانی فعل کے ذریعے سے اپنے آپ کو مستوجبِ سزا ٹھیرایا ہے، اور اس شخص کے بارے میں آپ بے حس ہیں، جسے ظلم اور سنگ دلی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص معاشرے کے اندر جرم کا ارتکاب کرکے معاشرے کے امن و سکون کو غارت کرتا ہے، وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو اتنی سخت سزا دی جائے کہ دوسروں کو اس سے عبرت ہو، اور وہ اس قسم کے جرم کے ارتکاب کی جرأت نہ کرسکیں۔ یعنی ہمارے نزدیک سزا صرف سزا ہی نہیں ہے بلکہ وہ ارتکابِ جرم کو روکنے کا ذریعہ بھی ہے اور وہ جرم کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ چنانچہ ہماری ہمدردی مجرم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس شخص کے ساتھ ہے، جس پر ارتکابِ جرم کیا جاتا ہے ، اور اس معاشرے کے ساتھ ہے جس کے اندر ارتکابِ جرم سے ناہمواری اورعدم تحفظ کی کیفیت پیدا کی گئی ہے۔
You think it is more social and more cultrued to be a criminal human. It is human to kill a man and it is inhuman to kill a murderer.
ابھی پچھلے دنوں امریکا میں مس ہیرسٹ ٭کا جو واقعہ پیش آیا ہے، وہ آپ کے علم میں ہوگا۔ جو لوگ اس کو اغوا کرکے لے گئے اور انھوں نے اس کو اس حد تک جرائم آشنا کردیا کہ اس نے بنک پر ڈاکا ڈالا اور دوسرے جرائم کا ارتکاب کرتی پھری۔ آپ کے نزدیک وہ لوگ تو بہت مہذب (Cultured) ہیں ،لیکن اگر ان لوگوں کو کوئی سخت سزا دی جائے تو یہ فعل غیرمہذبانہ ہوگا۔
۲۵ نومبر ۱۹۷۵ء : بی بی سی کے نمائندے ولیم کرالے کے انٹرویو سے ماخوذ
_______________
٭ اکیس سالہ مس پیٹریکا کیمبل ہیرسٹ (پ:۱۹۵۴ء) کو اغوا کرنے والوں نے، جو اپنے آپ کو بائیں بازو کی دہشت گرد تنظیم ’سمبائیونیزلبریشن آرمی‘ (SLA) کہتے تھے، ۱۹ماہ تک گرفتار رکھ کر مسلسل جرائم کی تعلیم دی اور ڈکیتی و راہ زنی کی بڑی بڑی وارداتوں میں استعمال کیا۔ وہ ۱۸ستمبر ۱۹۷۵ء کو گرفتار ہوئی، مقدمہ چلا اور ۳۵برس کی قید سنائی گئی، جسے امریکی صدر بل کلنٹن نے اپنے دورِ صدارت میں رہائی دلائی۔ ادارہ
انکارِ آخرت وہ چیز ہے جو کسی شخص ، گروہ یا قوم کو مجرم بنائے بغیر نہیں رہتی۔ اخلاق کی خرابی اس کا لازمی نتیجہ ہے اور انسانی تاریخ شاہد ہے کہ زندگی کے اِس نظریے کو جس قوم نے بھی اختیار کیا ہے، وہ آخرکار تباہ ہوکر رہی ہے۔
[سرکش قوموں کی گرفت کےبارے میں فرمایا گیا کہ] یہ لوگ تو اُس خوش حالی اور شوکت و حشمت کو پہنچ بھی نہیں سکے ہیں جو تُبّع [قبیلۂ حمیر کے بادشاہوں کا لقب جیسے کسریٰ، قیصر، فرعون وغیرہ]کی قوم، اور اُس سے پہلے سبا اور قومِ فرعون اور دوسری قوموں کو حاصل رہی ہے۔ مگر یہ مادّی خوشحالی اور دُنیوی شان و شوکت اخلاقی زوال کے نتائج سے اُن کو کب بچا سکی تھی کہ یہ اپنی ذرا سی پُونجی اور اپنے ذرائع و وسائل کے بل بوتے پر اُن سے بچ جائیں گے۔
جو شخص بھی حیات بعد الموت اور آخرت کی جزا و سزا کا منکر ہے، وہ دراصل اس کارخانۂ عالم کو کھلونا اور اس کے خالق کو نادان بچّہ سمجھتا ہے۔ اِسی بناپر اُس نے یہ رائے قائم کی ہے کہ انسان دُنیا میں ہر طرح کے ہنگامے برپا کرکے ایک روز بس یونہی مٹی میں رَل مِل جائے گا اور اس کے کسی اچھے یا بُرے کام کا کوئی نتیجہ نہ نکلے گا، حالانکہ یہ کائنات کسی کھلنڈرے کی نہیں بلکہ ایک خالق حکیم کی بنائی ہوئی ہے، اور کسی حکیم سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ فعلِ عبث کا ارتکاب کرے گا۔
انکارِ آخرت کے جواب میں یہ استدلال قرآنِ مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔
(’تفہیم القرآن‘ ، سورۃ الدخان سیّدابوالاعلیٰ مودودی، ترجمان القرآن، جولائی ۱۹۶۵ء، ص ۲۶-۲۷)