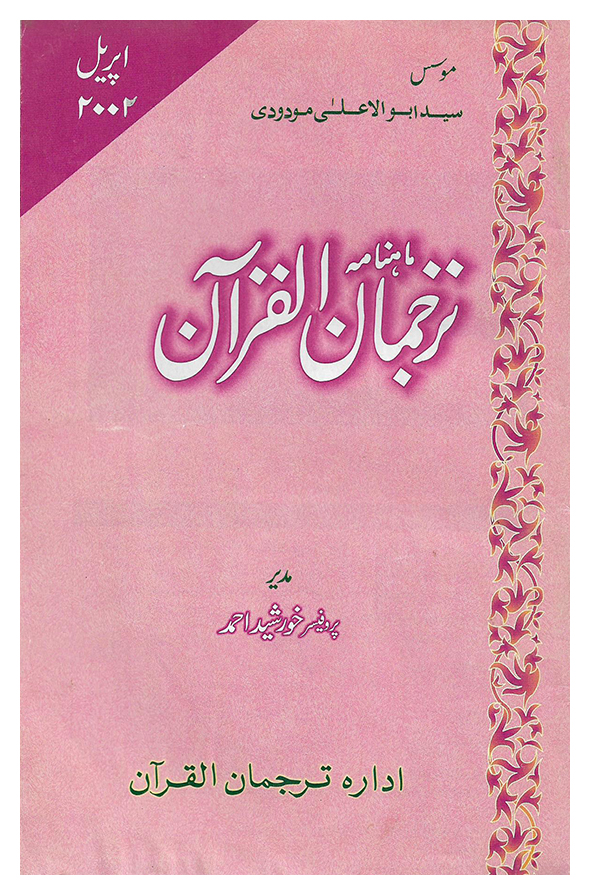
ترجمہ و تلخیص :مسلم سجاد
۱۱ ستمبر کے بعدکی ’نئی دنیا‘ میں امریکہ اور یورپ کے درمیان تعلقات کے حوالے سے برطانوی ہفت روزہ اکانومسٹ کا یہ مطالعہ یقینا ہمارے قارئین کے لیے دل چسپی کا باعث ہوگا۔
آج امریکہ اور یورپ کو ایک ایسے مسئلے کا سامنا ہے جو آنے والے عشروں میں ان کے تعلقات پر اثرانداز ہوگا۔ یہ مسئلہ عراق ہے۔
امریکی انتظامیہ فیصلہ کر چکی ہے کہ صدام حسین کی حکومت کا تختہ اُلٹ دیا جائے۔ مسئلہ اب صرف کب اور کس طرح کا ہے اور اسی سے امریکہ اور یورپ کے باہمی تعلقات کے بارے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یورپ کو فوری طور پر جس مسئلے کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ صدام کا تختہ اُلٹنے میں امریکہ کا ساتھ دے یا نہ دے‘ اور بش انتظامیہ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر یورپ تعاون پیش کرے تو بھی قبول کیا جائے یا نہیں۔ اگر وہ یہ تعاون قبول کرے تو اس سے کمیونزم کے خلاف ۲۰ ویں صدی کے دوسرے نصف کی جنگ کی طرح ۲۱ ویں صدی کے اوائل کی جنگ میں مغربی محاذ کی تشکیل ہوگی۔ عراق کا مسئلہ یورپی رائے عامہ میں متنازع ہوگا جیسا کہ یقینا ہوگا‘ تب بھی یہ تعلق مضبوط ہوگا--- لیکن اگر یورپی ممالک ساتھ نہ دیں‘ یا بش ان کی پیش کش ٹھکرا دے‘ تب بھی لڑائی ہوگی لیکن یہ صرف امریکہ کی کارروائی ہوگی۔
یورپ غیر متعلق نہیں ہو جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں اس کا اہم کردار جاری رہے گا۔ لیکن اگر یورپ کو کنارے لگا دیا گیا تو نئے ایجنڈے کا تعین اور اس کی قیادت امریکہ کرے گا اور یورپ کا اس حوالے سے کوئی کردار نہیں ہوگا کہ مستقبل کے خطرات کا سامنا کس طرح کیا جائے۔ کسی فریق نے ابھی طے نہیں کیا ہے کہ کیا کرنا ہے لیکن فیصلے جلد کیے جانے ہیں جو نہ صرف عراق بلکہ امریکہ اور یورپ کے مستقبل کا بھی فیصلہ کریں گے۔
مسٹر بش کی ’’برائی کے چکر‘‘والی تقریر کے جواب میں یورپ میں بڑا شور مچا ہے۔ فرانس‘ جرمنی اور یورپی برادری کی جانب سے ناراضی کا اظہار کیا گیا ہے۔ فرانس کے وزیرخارجہ کے بقول یورپی ممالک محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ غصے میں دہشت گردی اور مشرق وسطیٰ کے مسئلے کی بنیادی وجوہات کونظرانداز کر رہا ہے۔ جب مسٹر بش القاعدہ کے خلاف اتحاد کی آواز بلند کر رہے تھے تو فلسطینی ریاست کا تذکرہ ہوا لیکن اس کے بعد سے امریکہ ایریل شیرون کی غنڈا گردی کی پالیسیوں کو مسلسل ہری جھنڈی دکھا رہا ہے۔ یورپی ممالک کا خیال ہے کہ صدام کو ہٹانے سے پورا علاقہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا لیکن امریکہ عرب عوام کی رائے کو حقیر گردان کر اس کے لیے تیار ہے۔
یورپی ردعمل پر امریکہ کے غم و غصے کو کھل کر رپورٹ نہیں کیا گیا ہے۔ کولن پاول نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ امریکی رویے سے غیر مطمئن عناصر سے بات کریں گے لیکن دوسرے صاف کہتے ہیں: ’’یہ مغربی تہذیب کی جنگ ہے۔ اگر یورپی ممالک اپنے کو اس کا حصہ سمجھنے سے انکار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ دست بردار ہونا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ ہم انھیں اپنی حاشیہ برداری کرنے دیں گے!‘‘
یورپ میں دو رائے ہیں: ایک یہ کہ ایران‘ عراق اور شمالی کوریا کے لیے ہماری اپنی پالیسی ہونا چاہیے اور ہمارے لیے صدام کا تختہ اُلٹنے میں ساتھ دینا ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری رائے مسٹر بلیئر کی ہے کہ ہمیں صدام کو تباہ کن اسلحہ بنانے اور استعمال کرنے سے روک دینا چاہیے۔ اگر یورپ تعاون کی پیش کش کرے تو اس پر امریکہ میں تین رائے ہیں۔ پہلی دو کے مطابق اس پیش کش کو مسترد کر دینا چاہیے مگر ان کی وجوہات مختلف ہیں۔
پہلی کے مطابق ماوراے اوقیانوس اتحاد سے جو کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا کیا جا چکا ہے۔ عراق کے لیے کوئی مدد لی جائے تو وہ بجائے نیٹو کے انفرادی طور پر ممالک کی جانب سے ہو‘ جیسے آسٹریلیا اور کویت سے۔ آخر خلیج کی جنگ بھی اسی طرح لڑی گئی۔ اس رائے کے مطابق صدام کے زیادہ خطرناک اسلحے بنانے سے پہلے بہت کم وقت ہے۔ یورپ کو ساتھ لینے میں وقت ضائع ہوگا اور موقع نکل جائے گا۔
دوسری رائے کے مطابق نیٹو کو سرد جنگ کے نامکمل ایجنڈے کو مکمل کرنے میں مصروف رہنا چاہیے اور یورپی سلامتی کے نظام میں روس اور یوکرائن کو شامل کرنا چاہیے۔ تقسیم کار ہو‘ امریکہ بڑی جنگیں لڑے اور یورپی ممالک اپنی توجہات یورپ پر رکھیں اور باقی دُنیا امریکہ کے لیے چھوڑ دیں۔
تیسرے نقطہء نظر کے مطابق یورپی ممالک سے تعاون اور اشتراک ہونا چاہیے۔ نیٹو کا تعلق صرف یورپ کے دفاع سے نہیں ہے بلکہ مغرب پر اثرانداز ہونے والی تمام باتوں کے دفاع سے ہے۔ اس لیے اسے دہشت گردی اور تباہ کن اسلحے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
بحث کا اصل نکتہ یہ ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ مشترکہ طور پر کیا جائے یا علیحدہ۔ امریکہ کے نقطہء نظر سے تین سوال ہیں: ۱- کیا ہم یورپ پر بھروسا کر سکتے ہیں؟ ۲- ہمیں ان سے کیا فائدہ ہوگا؟ ۳-جب انھیں اپنے مفاد کے مطابق ہی چلنا ہے تو کیا ہمیں ان کی بات سننا چاہیے؟
بہت سے یورپی ممالک امریکہ کے یک طرفہ انداز سے ناخوش ہیں اور اس کے بارے میں کچھ نہ کرسکنے کی اپنی کیفیت پر چیں بجبیں ہیں۔ دوسرے ‘اپنی بے بسی کا احساس کرتے ہوئے امریکہ سے تعلق توڑنا نہیں چاہتے۔ اٹلی اور اسپین کے وزراے اعظم نے برائی کے چکر والی تقریر کو خوش آمدید کہا۔ برطانیہ بھی ‘ کم سے کم مسٹر بلیئر کے منہ سے صحیح بات ہی کہہ رہا ہے لیکن جرمنی اور فرانس کا علیحدہ معاملہ ہے۔ مختصر یہ کہ یہ یورپ کی طویل تاریخ میں امریکہ کے اقدامات سے مطابقت پیدا کرنے کا ایک اور موقع ہو سکتا ہے۔
امریکہ کو اولیت دینے والے کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ یورپی ممالک صدام کے خلاف سیاسی حمایت کریں لیکن اس کا عملی فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے دفاعی بجٹ شرم ناک حد تک کم ہیں۔فوجی ٹکنالوجی میں وہ ہم سے ایک نسل پیچھے ہیں۔ افغانستان میں ہمیں ان کی ضرورت نہ تھی۔ اس استدلال کو مسترد کرنا مشکل ہے اس لیے کہ یہ ایک حد تک درست ہے۔ لیکن دوسری رائے کے لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان کے وقت امریکہ انتظار نہ کرسکتا تھا۔ عراق کے معاملے کی یہ صورت حال نہیں ہے۔ اس نقطہء نظر میں یورپ کی عسکری صلاحیت مسلسل کم ہونے کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے۔ پوری دُنیا میں دفاع پر جو اخراجات کیے جاتے ہیں امریکہ اس کا ۴۰ فی صد خرچ کرتا ہے۔ پنٹاگون کا بجٹ نیٹو کے سب سے زیادہ فوجی اخراجات کرنے والے ملک‘ یعنی برطانیہ سے ۱۰ گنا زیادہ ہے۔ وسائل کا یہ فرق ٹکنالوجی کے فرق میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ تعجب خیز نہیں کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کھلے عام یورپی ’’بونوں‘‘(pygmies) کے بارے میں پریشانی کااظہار کرتے ہیں۔ آنے والے سال میں امریکہ فوجی بجٹ میں جو چھلانگ لگانے والا ہے اس سے فوجی طاقت کے فرق میں مزید اضافہ ہوگا اور یہی بش انتظامیہ کے بارے میں یورپ میں خطرے کی گھنٹی کا سبب ہے۔ امریکہ میں اپنی فوجی طاقت کا شعور بیدار ہو رہا ہے اور یورپ اس کا احساس کرکے اس طاقت کے اطلاق اور اپنی کمزوری پر پریشان ہے۔
دونوں میں یہ فرق یورپی طاقتوں کی کئی برسوں کی غفلت کا نتیجہ ہے جنھوں نے اپنے بجٹ رفاہی خدمات پر صرف کرنے کو ترجیح دی۔ اسے جلدی تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور بہت سے اسے تبدیل کرنا چاہتے بھی نہیں۔ وہ جیسے حالات ہیں ان کو پسند کرتے ہیں۔ وہ مکھن کے بجائے بندوقیں نہیں چاہتے۔ اس لیے کہ وہ خطرے کو قریب محسوس بھی نہیں کرتے۔ یورپ کی کمزوری پر امریکی بالکل پریشان نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اس سے انھیں عمل کی آزادی ملتی ہے۔ اگر یورپ نے طاقت بڑھا لی تو فیصلہ سازی میں دخل مانگے گا۔ فی الحال کسی کا بھی مفاد نئے توازن قائم کرنے میں نہیں ہے۔
موجودہ صورت حال میں بھی یورپ کا حصہ صفر نہیں ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی نوعیت میں خفیہ معلومات کے تبادلے‘ نگرانی اور مالی پابندیوں کی اہمیت فوجی طاقت سے کم نہیں۔ اس لیے شبہات اور مشکلات سے قطع نظر یورپی ممالک صدام حسین کے خلاف مہم میں حصہ لینے پر رضامند ہو سکتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اصل بحث تیسرے سوال پر ہے کہ اگر یورپ کسی نہ کسی طرح امریکہ کی بات ماننے پر مجبور ہے تو کیا مسٹر بش کو یورپی ممالک کے خیالات کو وزن دینا چاہیے؟ کئی وجوہات سے‘ ایسا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ۱۱ ستمبر کے واقعات دونوں کو قریب لائے ہیں۔ القاعدہ کی نفرت کا دوسرا نشانہ یورپ ہے۔ ان کے جال یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کو بے اثر بنانے کے لیے یورپ کی پولیس اور جاسوسوں کی ضرورت ہے۔
لیکن تعاون کی ان وجوہات کا امریکہ میں کوئی وزن نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی انتظامیہ ہے جسے اپنی طاقت کا خوب احساس ہے۔ بیش تر افراد کے پاس اس سوال کا کہ کیا کیا جائے‘ ایک ہی جواب ہے: جو امریکہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر امریکہ یورپی ممالک کی مدد کے بغیر صدام کا تختہ اُلٹ دے تو کیا انھیں شکایت ہوگی؟ کیا وہ نیٹو اور یورپی برادری کی توسیع کے خلاف ہو جائیں گے؟ بلاشبہہ نہیں۔
تعاون کا سبب وہ کام ہو سکتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے کہ یورپی ممالک کریں چاہے یورپی ممالک اسے اپنے مفاد میں نہ سمجھیں۔ مثال کے طور پر وہ فتح کے بعد آگے بڑھ کر تعمیرنو کا کام کریں جسے امریکہ اپنے لائق نہیں سمجھتا۔
امریکہ عراق کے مسئلے پر روس سے جھگڑا نہیں چاہتا۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ روس اور نیٹو کا تعاون بڑھے اور اس کے لیے یورپی ممالک کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ پھر بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں یورپی ممالک کو امریکہ کے برابر یا زیادہ خفیہ معلومات اور سفارتی وزن حاصل ہے۔ اگر امریکہ عراق پریورپ کو نظرانداز کرے تو یورپ دنیا کے دوسرے اہم حصوں میں امریکہ کو نظرانداز کرسکتا ہے۔
امریکی انتظامیہ کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کانٹے کا سوال یہ ہے کہ اسے اقدام کرنے کی بلاروک ٹوک آزادی ہو یا یورپ کا لحاظ رکھے۔ اس کا جواب مسٹر بش ہی دے سکتے ہیں۔ مسٹر بش ماوراے اوقیانوس اتحاد کو ۲۱ ویں صدی میں ایک نیا جواز دیں یا ۱۱ ستمبر کی ہلاکتوں میں ایک کا مزید اضافہ ہو: ماوراے اوقیانوس اتحاد کا مستقبل! (ہفت روزہ اکانومسٹ‘ ۹-۱۵ مارچ ۲۰۰۲ء‘ ص ۳۰-۳۲)